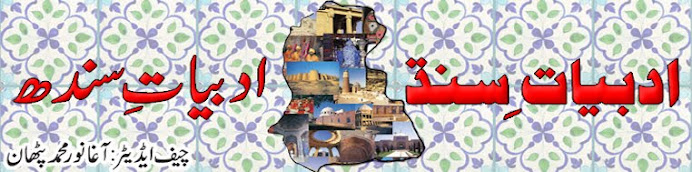Muhammad Ibrahim Joyo
PROFILE OF MR. MOHAMMAD IBRAHIM JOYO
Services Rendered In The Fields Of Education & Literature
- Introduction:
Name Mohammad Ibrahim Joyo
Father’s Name (Late) Mohammad Khan Joyo
Date of Birth August the 13th, 1915
Place of Birth Village Abad (Laki Teerath),
Laki Shah Saddar,
District Jamshoro, Sindh.
City Hyderabad.
CNIC No 41204-6613026-3
Postal Address House No-41/A,Sahafi Colony Near Allied Bank,Hyderabad, Sindh.
Pakistan.
Contact No 022-2612419
E mail Address ibrahimjoyo@yahoo.com
- EDUCATION:
B.A, B.T, (Bombay)
- Professional Record/Public Services:
| 1. | Assistant Master/Teacher Sindh Madarsah High School, Karachi. | April 1938 to August 1947. |
| 2. | Head Master, Municipal High School, Thatta. | September 1947 to May 1949. |
| 3. | Assistant Master, Training College for Men, Hyderabad | June 1949 to July, 1951. |
| 4. | Secretary, High Power Executive Committee for Sindhi Literature, Government of Sindh, Karachi. | July 1951 to February 1954. |
| 5. | Secretary, Sindhi Adabi Board, Karachi. | March 1954 to February 1961. |
| 6. | Publication Officer, Directorate of Education, Hyderabad Region, Sindh. | February 1961to November 1962. |
| 7. | O.S.D to the West Pakistan Text Book Board Lahore. | November 1962 to February 1963. |
| 8. | O.S.D to the West Pakistan Text Book Board, Incharge of the Board’s Regional Office at Hyderabad for Hyderabad, Karachi and Quetta Region. | March 1963 to July 1967. |
| 9. | Head Master, Government High School Jacobabad. | July 1967 to March 1968. |
| 10. | Principal, Government Training School, Kohat | March 1968 to November 1969. |
| 11. | Registrar, Departmental Examinations, Directorate of Education, Hyderabad | November 1969 to September 1970. |
| 12. | Deputy Director of Education (Schools) Hyderabad, Sindh. | September 1970 to January 1971. |
| 13. | Secretary, Sindh Text Book Board Hyderabad, Sindh. | February 1971 to August 1971. |
| 14. | Inspector of Schools, Khairpur, Sindh. | September 1971 to July 1972. |
| 15. | Deputy Director, Education Extension and Specialized Services, Hyderabad, Sindh. | July 1972 to September 1972. |
| 16. | O.S.D to Sindh Text Book Board, Hyderabad, Sindh. | September 1972 to August 1973. |
D. Honorary Membership/Services:
| a. Government Organization | |||
| 1. | Member Sindh Text Book Board, Hyderabad, Sindh. | August 1973 to June 1974. | |
| 2. | Honorary Chairman Sindhi Adabi Board. | 1997 to 2002. | |
| 3. | Member Board of Governors, Sindhi Language Authority. | 1998 to 2002. | |
| 4. | Member Financial, Publication and Research Committee of Sindhi Language Authority. | 1998 to 2002. | |
| 5. | Executive Member of Sindhi Language Authority. | 2001 to 2002. | |
| 6. | Member of Advisory Board Shaikh Ayaz Chair, Shah Abdul Latif University, Khairpur, Sindh. | 2000 to date. | |
| 7. | Member Board of Governors Sindhi Language Authority | 2008 to date. | |
b. Non-Government literary Forums/Social Organizations | |||
| 1. | Member Sindh Adabi Sangat. | 1954 to date. | |
| 2. | Founder President Sindhi Adiban Ji Sahkari Sangat Hyderabad. | 1973 to date. | |
| 3. | Founder President/Chairman Sindh Friend Circle. | 1978 to date. | |
| 4. | Sub-Editor, Sindh Quarterly, Karachi | 1982 to 2000. | |
| 5. | Vice President, Servants of Sindh Society. | 1982 to-date. | |
| 6. | Vice Chairman/Trustee Sindh Education Trust, Hyderabad. | 1995 to date. | |
| 7. | Chairman Shaikh Ayaz Foundation, Hyderabad. | 1998 to-date. | |
| 8. | Vice President, Theosophical Society, Hyderabad. | 1988 to 2006. | |
| 9. | President Theosophical Society, Hyderabad. | 2006 to-date. | |
| 10. | Vice President, Sindh Democratic Forum. | 2001 to-date. | |
| 11. | President, Sindh Rotary Club, Hyderabad. | January to December 2007. | |
E. LITERARY SERVICES RENDERED BY MOHAMMAD IBRAHIM JOYO:
a. Published Sindhi Books (Original writings):
1. SHAH – SACHAL – SAAMI: (1689-1850) – A STUDY
(1st Edition, 1978, 5th Edition, 1990).
2. MANHOO’A JO BHAAG
Plays, Tales, Folk Tales, Poetry, etc. (1st Edition, Sep: 1980, 2nd Edition, June 2004).
3. AURATA’ZAAD
(1983).
4. ASSAAN JI BOLEE ASSAAN JI TA’ALEEM
(1985).
5. MUTH MUTH MOTIYAN JI
(Selected writings published in Sindhi weekly HIDAYAT, Hyderabad, 1992).
6. HOO’A JA TIMKAY BAHIREE (4 Volumes)
(Volume-I: 1995).
7. ADAB-BOLEE-TA’ALEEM
(2nd volume of HOO’A JA TIMKAY BAHIREE, September1998).
8. GALHYOON KITABAN JOON - Volume-1
(3rd volume of HOO’A JA TIMKAY BAHIREE, June 2001).
9. GALHYOON KITABAN JOON - Volume-II,
(4th volume of HOO’A JA TIMKAY BAHIREE, June 2002).
10. KHAT’a BIN ADEEBAN JA
(Correspondence between Abdul Qadir Junejo and Mohammad Ibrahim Joyo,1999).
11. KHAT’a BIN USTAADAN JA
(Correspondence between Mohammad Ibrahim Joyo and Ghulam Ali Channa, 2003).
12. SUD PARRA’ADO
(2003).
13. PYAR – NIBAAR AIN ATHAH
(Correspondence between Mohammad Ibrahim Joyo and Ibn Hyat Panhwar, 2007).
14. SECULARISM AIN AQLYAT PASANDI
(2007).
15. SINDH MUNHINJAY KHUWABAN JEE
(2008).
b. Translations:
1. ISLAM JO TAREEKHI KARNAMO
(Sindhi Translation of M.N. Roy’s Book “Historical Role of Islam”,1945).
2. EMILEE URF TA’ALEEM
(Sindhi Translation of J.J Rousseau’s book “Emile or Education” 1st edition, 1949),
(4th edition, 1995).
3. BAARAN JI TA’ALEEM
(Sindhi Translation of Plutarch’s book “Education of Child”, 1st edition, 1972),
(2nd edition, 1995).
4. WAHISHEE JEEWAT JA NISHAN
(Sindhi Translation of Howard Moore’s book “Savage Survivals”, 1st edition 1976, 2nd edition, 1994).
5. GALLILEO
(Sindhi Translation of Bretolt Brecht’s play, “The Life of Galileo”, 1st edition September, 1977, 2nd edition 1997, 3rd edition 2007).
6. FIKR JI AAZADI
(Sindhi Translation of Stefan Zweig’s book “The Right to Heresy” 1st edition, June 1977, 2nd edition, 1997, 3rd edition 2007).
7. BAARAN JO MASSEEH
(Sindhi Translation of Enid Blyton’s book “Children’s life of Christ” 1980, 2nd edition 2008).
8. FALSAFAY JO IBTIDAI COURSE
(Sindhi Translation of George Polieser’s book. “An Elementary Course in Philosophy”, 1984, 2nd edition 2008).
9. MEHKARI’a JA MAZMOON’a By G.M. Mehkri
(Sindhi Translation of G.M. Mehkri’s Articles, 1st Edition, 1983, 2nd edition, 1985).
10. ILM-E-TADREES MAZLOOMAN LAA’E
(Sindhi Translation of Paulo Freire’s book, “Pedagogy of the Oppressed”, 1984).
11. FRENCH INQUILAB – I
(Sindhi Translation of Emile Erckmann and Alexander Chatrian’s Book English translation “The story of a Peasant”, 1990).
c. Published Urdu Book:
1. SINDH KAY SOOFI SHA’IR: (1997).
d. Published English Books:
1. SAVE SINDH – SAVE THE CONTINENT
(1st Edition June 1947, 2nd Edition, August 2002).
2. BETRAYAL: SINDH BIDES THE DAY FOR FREEDOM (3 Volumes), (English Writings, Preface/Forewords, Correspondence, Interviews etc. 1942-2007), Published in 2007.
3. SINDHU DESH – A NATION IN CHAINS (English Translation of G. M.Sayed’s Book, “Sindhu Desh - Chho Ai’n Chha laa’e), 1st Edition 1974.
4. NATIONAL UNITY (English Translation of G. M.Sayed’s Book, “Qaumi Ittehad”, Translated from Sindhi, 1978).
5. SHAH, SACHAL, SAMI (TRANSLATION), 2008.
F. Books under Publication:
1. SINDH BACHAYO - KHUND BACHAYO (Save Sindh – Save the Continent)
(TRANSLATION), 2010.
2. ORYUM KAY AHWAAL (Articles, Writings, Translations, Poetry, Preface/Forewords, Correspondence, Interviews etc. 1999-2010).
3. TALEEMI PADHAR NAAMO, (2010).
4. KHAT ADIBAN, AALMAN AIN DOSTAN JA, (Volume-I, 2010).
5. ON SINDH – A COMPILATION OF ARTICLES (By: DR. G.M MEHKRI, 2010).
6. “MY DEAR JOYO JI” (Letters) By DR. G.M MEHKRI (A Compilation), 2010.
G. ARTICLES/NEWSPAPER COLUMNS
NUMBER OF ARTICLES/COLUMNS PUBLISHED IN DAILY NEWSPAPERS AND DIFFERENT MAGAZINES OF SINDHI AND ENGLISH LANGUAGES (Daily Kawish, Ibrat, Awami Awaz, Daily Dawn etc.). MR. MOHAMMED IBRAHIM JOYO STARTED WRITING NEWSPAPER ARTICLES/COLUMNS IN 1942. HIS FIRST ARTICLE NAMED “LET US MAKE A CHOICE” WAS PUBLISHED IN WEEKLY “FREEDOM CALLING” BOMBAY ON NOVEMBER THE 7TH, 1942.
H. BOOKS UNDER COMPILATION/CONSIDERATION
1. KHAT ADIBAN JA, (Volume-II, 2010).
2. MUHINJA BUZRUG, DOST, SAATHI, (2010).
3. FRENCH INQALAB (Sindhi Translation) Volume-II,
I. Text Books
1. SINDHI PRIMER
2. ACHO TA GUDJEE PARHOON
3. SINDHI READER, CLASS PAHRYOON (ONE)
4. SINDHI READER, CLASS CHOTHOON (FOURTH)
5. SINDHI SUPPLEMENTARY READER, CLASS CHOTHOON (FOURTH)
6. SINDHI IKHTYARI KITAAB, CLASS CHHAHOON (SIXTH)
7. SINDHI READER, CLASS BIYO (TWO)
8. SINDHI READER, CLASS CHHAHOON (SIXTH)
9. SINDHI NISAB, CLASS (IXth & Xth)
10. SINDHI BOLI’A JO KITAAB, CLASS (XI & XII).
11. SAMAJI ABHYAS (For IX & X Classes) Sindhi Translation of Text Books. (Authors; Professor
Noor-ul-Karim & Mr. Kaleem-ud-din Peeyan, August 1961).
J. BOOKS EDITED
1. THE SINDHI INSTRUCTOR
By, Munshi Anandram, 1905
Revised by : Mohammad Ibrahim Joyo, 2nd edition, 1971, 3rd edition, 1983.
2. A MANUAL OF SINDHI LANGUAGE
By : Dulamal Boolchand, 1901 (English), Revised by Mohammad Ibrahim Joyo,
2nd edition, 2004.
3. SINDHI ZABAN JI BUNYADI LUGHAT (Sindhi)
Prepared with co-authors, 1976.
NUMBER OF BOOKS OF SINDHI ADABI BOARD, SINDH TEXTBOOK
BOARD, SINDHI LANGUAGE AUTHORITY, SINDHI ADEEBAN JI
SAHKARI SANGAT, SINDH EDUCATION TRUST, SHAIKH AYAZ
FOUNDATION, SINDH FRIENDS CIRCLE, published under
the supervision and editing of Mohammad Ibrahim Joyo.
- TEXT BOOKS (PRIMARY TO MATRICULATION)
Written and translated, total number 30.
- PREFACES / FOREWORDS TO BOOKS:
Total number 70.
- 10. BOOKLETS ON DIFFERENT ISSUES PUBLISHED:
Sindhi : 8
English : 5
- POEMS:
Total number : 22.
K. INSTITUTIONS ESTABLISHED BY MUHAMMAD IBRAHIM
JOYO IN COLLOBORATION WITH OTHER FRIENDS.
1. SINDH RENAISSANCE ASSOCIATION, KARACHI, 1946.
2. MUSIC LOVERS’ CLUB, 1968.
3. SINDHI ADEEBAN JEE SAHKARI SANGAT, HYDERABAD, 1973.
4. SINDH FRIENDS CIRCLE, HYDERABAD, 1978.
5. SINDH RENAISSANCE CLUB, HYDERABAD, 1994.
6. SINDH EDUCATION TRUST, HYDERABAD, 1995.
7. SHAIKH AYAZ FOUNDATION, HYDERABAD, 1998.
8. SINDHI LOK RAAG SIKHYA MARKAZ, HYDERABAD, 2000.
سندھ کے صوفی شعراء کا پیغام محبت
سندھ کے صوفی شعراء کا پیغام محبت
آج کی تضادات سے پر دنیا میں انسانذات ہیجان، انتشار اور تشدد کا شکار ہے اور رنگ و نسل، مذہب، ذات پات، فرقیواریت اور لسانی تعصبات کی بنیاد پر تقسیم ہوچکی ہے، حالات اسے نفرت، انتہا پسندی اور دہشتگردی کی طرف دھکیل رہے ہیں جسکی وجہ سے اس کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے- عام آدمی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے، حتیٰ کی دانشور اور اہل علم بھی مایوس اور قنوطیت پسند بن کر بے عمل اور غیر فعال ہوکر بیٹھ گئے ہیں- اس صورتحال نے عوام میں مایوسی اور بیزاری پیدا کردی ہے- ایسے حالات میں تلخ حقائق سے فرار حاصل کرنے کے لئے عموماً لوگ یا تو مذہب میں پناہ ڈھونڈتے ہیں یا کوئی اور فرار کا راستہ اختیار کرلیتے ہیں، تاہم معروضی حقائق ایک تیسرا راستہ اختیار کرنےکا مطالبہ کرتے ہیں جو ہے صوفی ازم!
مذہب، جو انسان کو ذہنی و روحانی سکون اور احساسِ تحفظ دینے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اسے عصر حاضر میں اسکی روح سے جدا کر کے محض چند رسوم کی تقلید بنا دیا گیا ہے- مذہب کے ظاہری خدوخال پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے مسالک کے درمیاں اختلاف کو فروغ حاصل ہوا ہے اس کے علاوہ ملائیت اور طالبانائیزیشن کے منفی اثرات کے نتیجے میں بھی لوگوں کے طبقات ان کی حمایت و مخالفت میں ظاہر ہوئے ہیں- ان وجوہات کی بناپر کئی نوجوان اور معاشرے کے تعلیم یافتہ افراد مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ دراصل ظاہری رسومات اور ارکانِ عبادت مذہب کا صرف ایک رخ ہیں۔ اس کا دوسرا اہم رُخ اور اصلی اور باطنی پہلو وہ فہم و ادراک ہے جو انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بلندی عطا کرتا ہے اور اسے ناامیدی کے وقت دلی تسکین دیتا ہے- آج کے دور میں مذہب کا وہ جوہر کہیں گم کردیا گیا ہے، روایتی مذہبی اور ظاہر پرست افراد بھلے ہی اپنے عقیدےکو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہوں، ان کی اپنی روحیں اس اصلی جوہر کو پانے سے محروم ہیں جس سے دل و دماغ منور ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو رواداری، محبت اور امن کے عظیم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کا دعوہ تو کرتے ہیں مگر ان ہی عظیم شخصیات کے درس کے مطابق دوسروں کے عقیدوں کا احترام بھول جاتے ہیں، ان کو اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں کہ ایک انسان اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے بھی دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ باہم اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے۔
ایسے حالات میں رہنمائی کےلئے آخر کس کی طرف دیکھیں؟ کون ہے جو دینا کو پھر سے امن کا گہوارہ بنانے میں ہماری مدد کرسکتا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو تمام مذاہبِ عالم کے اندر موجود واحد ایسے جوہر میں یقین رکھتے ہوں، ایسے لوگ جو یہ سمجھیں کہ مذاہب اپنی ظاہری اشکال، رسمی اطوار، زبان و اصطلاحات میں تو فرق رکھتے ہیں مگر ان کے اندر انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے تصور میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوتا ایسے لوگ جن کا عقیدہ ہوکہ اپنے خالق کی نظر میں تمام انسان بغیر کسی تفریق کے برابر ہیں "صوفی" ہوتے ہیں، جو محبت، رواداری، برداشت کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ تمام عالم انسان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ایک صوفی کا نظریہ کسی مذہب، عقیدے یا مسلک سے متصادم نہیں ہوتا بلکہ یہ ان تمام مذاہب اور عقائد کے جوہر سے آشنا لوگ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی ضرورت آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ہے، جب لوگوں کے ذہن انتشار کا شکار ہیں اور معاشرہ اخلاقی و روحانی پستی کی طرف گامزن ہے- تصوف کی تعمیل کرنے کی اس لئے بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ تفریق اور امتیاز کے خلاف ایک تحریک ہے جو مختلف ادوار میں صوفیائے کرام چلاتے رہے ہیں۔ تصوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور انہیں ایک ہی خالق حقیقی نے تخلیق کیا ہے، جو بلا تفریق سب سے یکسان محبت کرتا ہے، حقیقی صوفیوں کا مانناہے کہ جو ایک کا عقیدہ ہے وہ دوسرے کی نظر میں کمتر نہیں ہونا چاہئے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ "تم جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو اور جو اپنے لئے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لئے بھی چاہو"۔
Mysticism (تصوف) ایک وسیع اصطلاح ہے جو ایسے عقیدے کے لئے استعمال ہوتی ہے جو تمام مذاہب کے جوہر اور روح میں یقین رکھتا ہے مگر مختلف مذاہب کے لوگوں میں اس کے مختلف نام پائےجاتے ہیں۔ مثلاً کبالہ، بھگتی، موکشا اور صوفی ازم وغیرہ۔ اس کی تمام تشریحات ایک نکتے پر متفق ہیں کہ ہر مذہب کا ایک باطنی پہلو ہوتا ہے جس پر عمل کرکے انسان "خودشناسی" کے ذریعے "خدا شناسی" کی راہ اختیار کرسکتا ہے۔
برصغیر میں بہت بڑے اور عظیم صوفیائے کرام گذرے ہیں جنہوں نے اسلام کا ایک بہت ہی سہل اور خوبصورت تصور (Soft image) عام کیا اور ان کی ایسی تعلیمات کےنتیجے میں لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، خصوصاً وادیء سندھ میں صوفی تحریک اس سرزمین کی رواداری، محبت، اُخوت، باہمی اشتراک اور امن کی روایات سے ہم آہنگ ہوکر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی اور لوگوں کی فطرت کا حصہ بن گئی، اس بات کا آج بھی بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ اب بھی مزاجاً صوفی ہوتے ہیں- وادیء سندھ کے صوفیائے کرام نے اسلام کا ایک دوستانہ، برادرانہ، پرامن، برداشت اور رواداری کے عناصر رکھنے والا تصور عام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسانوں کو عملی زندگی میں بھی فعال رہنے کا درس دیا۔ پنجاب میں فریدالدین گنج شکر اور داتا گنج بخش اور سندھ میں قلندر لعل شہباز اور عبدﷲ شاہ غازی ایسے صوفیائے کرام تھے، مگر جن لوگوں نے عوام الناس کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور اپنا گرویدہ بنا لیا وہ تھے صوفی شعرا جنہوں نے لوگوں کی اپنی زبانوں میں شاعری کی اور اپنا امن و آشتی، پیار و محبت کا پیغام عام کیا۔ پنجاب میں مادھو لال حسین، بلھے شاہ اور سندھ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست اورسامی نے اخوت، مساوات، محبت اور رواداری کے آفاقی پیغام دئے۔
سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف ظاہر پرست مولویوں اور پنڈتوں کے خلاف تھے جو لوگوں کو تعصب اور امتیاز کا سبق پڑھاتے تھے اور حق کی راہ سے ہٹ کر محض ظاہری رسوم ادا کرنے کو مذہب کا نام دیتے تھے۔ روز ہ، نماز اور دیگر عبادات تو کرتے تھے، لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی تبلیغ بھی کرتے تھے مگر ان کے اندر موجود روح کو بھلا بیٹھتے تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ :
روزا نمازون اي پڻ چڱو ڪم،
او ڪو ٻيو فهم جنهن سان پسجي پرينءَ کي
ترجمہ: روزہ نماز قابل تحسین عمل ہیں مگر جو فہم اور دانش اپنے محبوبِ حقیقی کا قرب حاصل کرنے کی لئے ضروری ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس خطہ زمین پر لوگ اپنے اپنے مذہب اور مسلک پر قائم رہتے ہوئے کبھی بھی انتہا پسند اور بنیاد پرست نہیں رہے نہ ہی انہوں نے عقیدے کےمعاملے میں کبھی جبر سے کام لیا۔ اور آج کے دور میں بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے۔
شاہ لطیف کا پیغام اس قدر رواداری کی مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں:
ڪوڙو تون ڪُفرسين ڪافر مَ ڪوٺاءِ
هندو هڏ مَ آهيين جڻيو تو نه جڳاءِ
تلڪ تنين کي لاءِ سچا جي شرڪ سين.
ترجمہ: اگر کوئی کافر اپنے کفر سے مخلص نہیں ہے تو اسے کافر کہلانے کا حق نہیں ہے- ایسے ہندو کو "جنیہ" پہننے کا حق بھی نہیں اور صرف ایسے لوگ تلک لگانے کے مجاز ہیں جو اپنے شرک سے سچے ہوں۔ اس طرح مسلمان کو بھی اپنے مسلک سے سچا اور مخلص رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر اعلیٰ انسانی اقدار کی بھی تبلیغ کی جن میں حب الوطنی، نصب العین کے حصول کے لئے جدوجہد، قربانی، مستقل مزاجی، پاکیزگی وغیرہ شامل ہیں۔
تتيءَ ٿڌيءَ ڪاهه، ڪانهي ويل ويهڻ جي،
متان ٿئي اونداه، پير نه لهين پرينءَ جو.
ترجمہ: موسم گرم ہو یا سرد، اپنا سفر جاری رکھو کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، ایسا نہ ہوکہ اندھیرا ہوجائے اور تم محبوب کے نقشِ پا دیکھ نہ سکو!
جان جان هئي جيئري ورچي نه ويٺي،
وڃي ڀونءِ پيٺي، سڪندي کي سڄڻين.
ترجمہ: جب تک زندہ تھی اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرتی رہی، اپنے محبوب کے لئے ترستے ہوئے آخر کار موت کو گلے لگا لیا۔
آج کے دور میں صوفی ازم کو نئے سرے سے رواج میں لانے کی ضرورت تو ہے مگر، پچھلی چند صدیوں میں کچھ ایسی بدعتیں اوربرائیاں صوفی فلسفے کی نام سے رائج ہوگئی ہیں کہ پہلے ان کو اس نظام سے خارج کرنا ضروری ہے۔ آج "صوفی" لفظ کے معنیٰ بھی بدل گئے ہیں- بے عمل، کاہل اور منشیات کے عادی لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اس کے علاوہ پیری مریدی کےنام سے اصلی تعلیمات سے ہٹ کر توہم پرستی کو بڑھاوا دیا گیا ہے، آمرانہ اور نوآبادیاتی تسلط کے ادوار میں ایک ایسا نظام رفتہ رفتہ متعارف ہو چکا ہے جو صوفی ازم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث ہے اور لوگ مزاروں کے احاطوں میں پڑے رہنے کو صوفیوں کا راستہ سمجھنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفی بزرگان نے جو اپنے رب سے لؤ لگانے اور انسانوں سے محبت و اخوت کا پیغام دیا اسے بھول کر ان کی وفات کے بعد ان کے مزاروں کوعبادتگاہوں کا درجہ دیا گیا، ان کی اولادوں کو موروثی و خاندانی پیر قرار دیکر سجادہ نشینوں اور متولیوں کے روپ میں نذرانے دئے جانے لگے اورجب یہ کمائی کا ذریعہ بن گیا تو جعلی اور مصنوعی پیروں نے اسے کاروبار بنا لیا اور اپنی کرامات کے نام پر نرینہ اولاد اور مرادیں پوری کرنے والے پہنچے ہوئے بزرگ کا چولا پہن کر جادو، ٹوٹے، منشیات اور دیگر ایسی خرافات نکا عادی بناکر لوگوں کو معاشی اور معاشرتی سطح پر تباہ و برباد کرنا شروع کردیا۔
انگریزوں نے اور کئی مقامی حکمرانوں نے بھی اس نطام کو مزید مضبوط کیا۔ مورثی پیروں کے مال و ملکیت اور گدی کی ورا ثت سے متعلق آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان میں سے بعض کو اپنے منظور نظر بنا کر سیاسی نظام کا حصہ بنا لیا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے ماننے والوں اور مریدوں کی فوج تھی جو کسی حکمران کی وفادار اور تابعدار رعایا کا کردار ادا کرسکتی تھی۔
صوفی ازم کےنام پر ایسی تمام بدعتوں، توہم پرستی اور سیاسی مقاصد کے لئے استعمال سے دامن بچاکر آج کے دور میں صوفی ازم کو اس کی اصلی روح کے ساتھ انسانوں کے درمیان بھائی چارے اور امن و آشتی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ صوفی کٹر پن، بنیادپرستی اور انتہاپسندی کے خلاف ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جدید علوم نے روشن خیالی اور سکیولر سوچ کو عام کیا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانوں کے درمیاں ہر قسم کے امتیاز و تفریق سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور محبت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے کلچر کو فروغ دیا جائے- آج دنیا میں اسلام کا جو منفی تصور عام کیا جا رہا ہے، خصوصاً مغرب میں مسلمانوں کو بنیاد پرست اور دہشت گرد سمجھا جا رہا ہےاس تاثر کو زائل کرنے کے لئے اسلام کا نرم تصور (Soft image)پھیلانے کی ضرورت ہے جس کا آسان ترین طریقہ ہے صوفی شعرائ کے کلام کو عام کرنا۔
سندھ کے صوفی شعرا ء کی بین الاقوامیت اور آفاقیت کی مثال اس شعر سے بہتر کوئی ہوہی نہیں سکتی:
سائينم سدائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار
دوست مٺا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين (شاه)
ترجمہ: اے میرے سائیں میرے سندھ کو سدا خوشحال و سرسبز رکھنا- اے میرے محبوب رب تمام عالم کو بھی شاد و آباد رکھنا۔
اور سچل سرمست نے تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے ہی عظیم سمجھا ہے نہ کہ کسی مذہب، مسلک، رنگ و نسل کی وجہ سے- کہتے ہیں:
انسان هيس انسان آهيان،
هندو مومن ناهيان،
جوئي، آهيان سوئي آهيان،
ڪو مومن چوي ڪو ڪافر چوي،
ڪو جاهل نالو ظاهر چوي،
ڪو شاعر چوي ڪو ساحر چوي،
آءٌ جوئي آهيان سوئي آهيان.
ترجمہ: انسان تھا انسان ہوں
ہندو مومن نہیں ہوں،
میں جو ہوں سو ہوں،
کوئی مومن کہے کوئی کافر کہے،
کوئی جاہل نام ظاہر کہےم
کوئی شاعر کہے کوئی ساحر کہے-
میں جو ہوں سو ہوں۔
ایک اور جگہ سچل سرمست کہتے ہیں:
مذهبن ملڪ ۾، ماڻهو منجهايا،
شيخي پيري بزرگيءَ، بيحد ڀلايا،
ڪي نمازون نوڙي پڙهن، ڪن مندر وسايا،
اوڏو ڪين آيا، عقل وارا عشق کي.
ترجمہ: عقائد و مسالک نے لوگ الجھائے
شیخی پیری بزرگی نے بے حد بھلائے
کوئی محض نماز پڑھے کوئی مندر بسائے
کیوں یہ عاقل عشق کے قریب نہ آئے۔
اور یوں صوفی دل کی صفائی پر ایمان رکھتے ہوئے تمام عالم انسان کی بھلائی اور بہتری کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور یہی آج ہماری ضرورت ہے۔
استاد بخاري
استاد بخاري 1930کان 1992ع تائين
استاد بخاري جو پورو نالو احمد شاه بخاري هو. سندس جنم دادو ضلعي جي هڪ ڳوٺ غلام چانڊيو ۾ سيد حاجن شاه جي گهر ۾ ٿيو . شروعات ۾ پرائمري استاد جي حيثيت سان ڪم ڪيائين، بعد ۾ ڪاليج ۾ سنڌي ادب جو ليڪچرار مقرر ٿيو ۽ آخر ۾ پروفيسر ٿي دادو جي ڊگري ڪاليج مان رٽائرڊ ٿيو۔.
استاد بخاري 1950ع کان باقاعده مشاعرن ۾ شرڪت ڪرڻ لڳو ۽ سندس شعر مختلف رسالن ۾ شايع ٿيڻ لڳا. استاد بخاري جي سڃاڻپ هڪ عوامي شاعر جي حيثيت ۾ پوري سنڌ ۾ ٿي، سندس ڇپيل شعري مجموعن ۾ ” ڪوڪڻ ۽ ڪلياڻ“، ”ڪاري ڪڪر هيٺ“، 1991ع ، ”ڌرتي سرتي“ 1991ع ” نه ڪم نبريونه غم نبريو“، 1992ع، ”زندگي زندگي“ 1992ع ، ”پير هٽن پوئتي” 1992ع، ” اوتون جوتون“ 1994ع ” ماندي ٿي نه مارئي“ 1994ع، ولولو ۽ روڪ“ 1994ع، ”وطن ۽ ويساهه“ 1997ع ، ” هر ئي هيڄ وطن جا“ 1998ع، ”ٿڙ ٿڙ تيڏيان ڳالهايان“ (2000)، ”گهڙيا سي چڙهيا“ (2001)، ” گيت اسان جا جيت اسان جي“، ”لهر لهر دريا“، سوچون ڀڻڪا واڪا“، ”گيت گلابي ٻارن جا“، ” ميلا ملهالا“، ” لهر لهر ۾ لالاڻ“، ڳائي پيو جاڳي پيو“، ”گلدستي ۾ گيت“ ۽ ٻيا مجموعا آهن۔.
استاد بخاري سنڌي شاعري ۾ هڪ وڏو نالو آهي، هو شاعري جي افق تي عوامي ترجما نگار جي حيثيت سان اڀريو. سندس شاعري عشق، حسن ۽ قوميت جو سنگم آهي. راشد مورائي سندس شاعري لاءِ لکي ٿو ته ” استاد بخاريءِ سونهن، سچ ۽ پيار جو شاعر آهي ۽ انهن موضوعن کي نهايت سادي، سولي ۽ عام فهم ٻوليءَ ۾ اهڙو ته خوبصورتي سان پيش ڪيو اٿس، جو سندس شاعري ۾ چمڪ پيدا ٿي پئي آهي، ” استاد بخاري حسن ۽ عشق مان وڏو اتساهه ٿو وٺي، هو حسن ۽ عشق کانسواءِ زندگي جو تصور اڌورو ٿو سمجهي۔.
او عشق نه ڇڃ مون کان، او سونهن نه ڇڏ پاسو
نه ته مان ڊڄان ٿو پيو هن هانءُ جي دهڪن کان
استاد بخاري لفظن ۾ ساهه ڀرڻ سان گڏ لفظن ۾ جادو به ڀري ٿو. لفظ استاد اڳيان ڇيرو پائي نچندا نظر اچن ٿا. سندس شاعري جي سٽ سٽ ۾ حسن ۽ عشق جو پيغام آهي. هو چوي ٿو ته ؛
زندگي تي ناهين ڪوئي ڀروسو،
حسن کي پوجي وٺو پوجي وٺو
ڪائنات حسن ۾ هلندو وتان،
ڄڻ ته بحر حسن ۾ ترندو وتان،
حسن کي ڏسندو وتان ٺرندو وتان،
حسن ٿو ڏئي استاد ڏاڍو مزو
استاد حسن جي ڪائنات ۾ گذاريندي، وڇوڙو، رسڻ، پرچڻ، چوٽ، درد، سور، سوز، انتظاري، بيقراري جهڙين ڪيفيتن مان گذري ٿو. دل تي درد سهندي، برهه مان باهه ٻارڻ جو ڪيڏو نو سهڻو اظهار ڪيو اٿائين.
جيءُ جنهن کي چيم، جهڻڪ تنهن کان مليم
چوٽ ڏاڍي رسيم، پر ڪيم درگذر
ڪيس ڪيڏا ڪئي حسن جي انڌ تي
باهه ٻاري وڌءِ هانءَ جي هنڌ تي
غير جي پنڌ تي پير تنهنجا ڏٺم
چوٽ ڏاڍي رسيم، پر ڪيم در گذر
ڪو به اديب، شاعر، سگهڙ يا سياستدان پنهنجي قوميت کان دستبردار نه ٿيندو آهي. ڪيڏا به ساڻس ها ڃا ٿين، ليڪن انساني سڃاڻپ قوميت سان ئي منسوب آهي. استاد بخاري جا گيت، غزل، وايون ۽ باقي سڀ صنفون سنڌ ڌرتيءَ جي قوميت جي رنگ ۾ رنگيل آهن، ڇو جو خودئي وڏي واڪي چيو اٿائين ته؛
اغيار سان اقرار اهو ڪيئن ٿيندو
۽ يار سان انڪار اهو ڪيئن ٿيندو
استاد بخاري کي کڻي دفن ڪيو
ڌرتي کان مگر ڌار، اهو ڪيئن ٿيندو
سنڌ، جيڪا ڪراچيءَ کان ڪشمور ۽ ڪينجهر کان ڪارونجهر تائين پکڙيل آهي، ان لاءِ ” استاد“ چوي ٿو ته؛
سنڌو جي اٿل سمجهه عقيدا منهنجا،
منڇر جا ڪنول سمجهه عقيدا منهنجا
مهراڻ ۽ منڇر جي لٿل ٿا ڏسجن
اولاد لٿل سمجهه عقيدا منهنجا
استاد کي سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ سان محبت آهي، هتان جي ماروئڙن، جهانگيئڙن جا حالات زار ڏسي هو بي چين ٿي پوي ٿو؛
مان ڪيئن سيج سمهان، منهنجا ماروئڙا
منهنجا سانگيئڙا، پڌر پٽ سمهن
تنهنجي ميزن تي، سهسين کاڄ اچن
کائن ڪانگ ڪتا، جوٺا جام بچن
مان ڪيئن لوڻ چکان، منهنجا ماروئڙا
منهنجا سانگيئڙا، روزا روز رکن
استاد بخاري خاموش ٿي ويهي رهڻ کي غلط ٿو سمجهي، سنڌ جي مسئلن لاءِ وڙهڻ جي ترغيب ڏئي ٿو، هو مرشد جي فيض ۽ ڌرتيءَ لاءِ حق وٺڻ لاءِ چوي ٿو
سون مرشد کان ڳنهي وٺبو آ
فيض مرشد کان وٺبو آ
جو به سمجهو اوهان جو حق آ
حق مڙسي سان ڇني وٺبو آ
استاد بخاري هن ڌرتي جو نظرياتي سوچ وارو دانشور ۽ انقلاب جي علامت آه، ڪنهن وڏي منزل تي رسڻ تائين اهو ئي چوڻ به حق ٿو سمجهي ته؛
جو قوم جياري جئندو رهندو،
جو عام اجاري اهو جئندو رهندو
مون کي تاريخ ۽ تقدير ڏني پڪ آهي
جو سنڌ سنواري اهو جئندو رهندو
استاد بخاري جتي حسن، عشق ۽ قوميت جي ڳالهه ڪري ٿو، اتي بين الاقوامي امن، انسانيت کي به نٿو وساري، ڇو جو سندس شاعري صرف سنڌ جي سرحدن تائين محدود نه آهي. نفرت کي لعنت ٿو سمجهي، ذاتين، مذهبي فرقي بازن کي انسانيت لاءِ هاڃو ٿو سمجهي؛
ٿو ٿو ٿو ٿو، نفرت نفرت هيڙو هيڙو لعنت لعنت
ظلم جي هي ڇيڙ، جوڳي، جهٽ ڪر، ڇيڙون ڇيڙا
ڪلفت فتنا ۽ ناسازيون ذاتيون مذهب فني بازيون
سڀ تي پيار پکيڙ، جوڳي جهٽ ڪر ڇيڙون ڇيڙا
جڏهن دنيا ۾ ايٽم بم جي ايجاد سان وڏي پيماني تي تباهي ٿيڻ لڳي، تڏهن استاد چوي ٿو ته ؛
ايٽم هٿ ۾، انسان بڻيو، انسان جو ويري
يا ڪندا هي دنيا تنهنجو ڍينگوئي ڍيري
مطلب ته استاد پنهنجي سچ، سونهن، حسن، عشق، قوميت ۽ بين الاقواميت جي موضوعن سان سنڌي شاعري کي عظمت ۽ انفراديت بخشي . سندس شاعري جي سڀ کان وڏي خوبي اها آهي ته اها وڏي پيماني تي ڳائي وڃي ٿي ۽ ٻڌي وڃي ٿي سندسن شاعري جي عظمت ان وقت اڃان به وڌي وڃي جڏهن ان ۾ عوامي ترجماني جا سڀئي پهلو ملن ٿا۔ تحریر:مختیار ملاح
مولوي عبدالغفور مفتون همايوني
مولوي عبدالغفور مفتون همايوني؛ 1844ع 1918ع)؛ مولوي صاحب جي هڪ سنڌ ملوڪ ڪافي هيءَ آهي؛
تنهنجي زلف جي بند ڪمندا وڌا،
زندان هزارين مان نه رڳو.
تنهنجي شاهي دستر خوان مٿي،
مهمان هزارين مان نه رڳو
ڪيئي گهائل تنهنجي گهور سندا،
مخمور غفور سُروُر سندا،
تنهنجي نور ظهور حضور سندا،
نگران هزارين مان نه رڳو.
ڪيئي ابرو تيغ شهيد ڪيا،
ڪيئي ناز مزيد مُريد ڪيا،
ري ناڻي ديد خريد ڪيا،
دربان هزارين مان نه رڳو
اي ماهه لقا محبوب مٺا،
تنهنجي ناز ادا تان جان فدا،
ٿيا دامن گير امير گدا،
سلطان هزارين مان نه رڳو.
دلبر پيارا ڪر نور نظر،
تون ته سرور عالم جن و بشر،
تو تان ڪتيون تارا، شمس و قمر،
قربان هزارين مان نه رڳو.
۱۸۴۴-۱۹۱۸ نعت از مولوی عبدالغفور مفتون ھمایونی
تیرے زلفوں نے مجھے زنجیر ڈالے، قیدی ھزاروں فقط
تیرے شاھی دستر خوان پر، مہمان ھزاروں فقط میں نہیں
کئی گھایل ہوئے تیرے نور نظر سے
حضور میرے نگران ھزاروں فقط میں نہیں
تیرے انشارہ ابرو نے کئی، ناز انداز مرید کئے
تیری نظر نازاں نے کئی نامور نام خرید کئے
میرے جیسے درباں ہزاروں میں ،اے ماہ تھا محبوب تم میرے
تیرے ناز ادا پر جان فدا،ہوئے دامن گیر امری دا گدا،
سلطان ھزاروں میں، فقط میں نہیں
پیارے دلبر کر نور نظر
تو ہے سرور عالم جن و بشر
تم پر ہیں کہکشان، شمس و قمر
اور ستارے قربان ہزاروں، فقط میں نہیں
دلبر پیارے کر نور نظر
تو تو سرور عالم جن و بشر
تم پر ہیں قربان تمام شمس و قمر اور کہکشاں
فقط میں نہیں
Urdu Translation of Sindhi Poetry by Agha Noor Muhammad Pathan
مولوي عبدالغفور مفتون همايوني؛ 1844ع 1918ع
مولوي صاحب جي هڪ سنڌ ملوڪ ڪافي حضور نبي سرورِ ڪائنات سلی اللہ علیہ و سلم جي شان ۾
اردو ترجمہ: آغا نور محمد پٹھان
تنهنجي زلف جي بند ڪمندا وڌا،
زندان هزارين مان نه رڳو.
تنهنجي شاهي دستر خوان مٿي،
مهمان هزارين مان نه رڳو
ترجمہ:
تیرے زلفوں نے مجھے قید کیا، اسیران ھزاروں،
میں ہی کیا!
تیرے شاہی دستر خوان پر، مہمان ھزاروں
میں ہی کیا!
کئی گھایل ہوئے تیرے نوری نظر سے
مخمور و مسُرور ہوئے حیران ہزاروں
میں ہی کیا!
شاعري
ڪيئي گهائل تنهنجي گهور سندا،
مخمور غفور سُروُر سندا،
تنهنجي نور ظهور حضور سندا،
نگران هزارين مان نه رڳو.
ترجمہ:
پیارے دلبر کر نور نظر ، تو ہے سرور عالم جن و بشر
تم پر ہیں قربان، شمس و قمر
اور کہکشاں ہزاروں،
میں ہی کیا!
شاعري
ڪيئي ابرو تيغ شهيد ڪيا،
ڪيئي ناز مزيد مُريد ڪيا،
ري ناڻي ديد خريد ڪيا،
دربان هزارين مان نه رڳو،
ترجمہ:
تیرے اشارہ ابرو نے کئی، ناز انداز مرید کئے
تیری نظر نازاں نے کئی نامور نام خرید کئے
میرے جیسے درباں ہزاروں
میں ہی کیا!
شاعري
اي ماهه لقا محبوب مٺا،
تنهنجي ناز ادا تان جان فدا،
ٿيا دامن گير امير گدا،
سلطان هزارين مان نه رڳو.
ترجمہ:
اے ماہ لقا، محبوب میرے
تیرے پرُناز ادا پر جان فدا
ہوئے دامن گیر امیر و گدا سلطان ہزاروں
میں ہی کیا!
شاعري
دلبر پيارا ڪر نور نظر،
تون ته سرور عالم جن و بشر،
تو تان ڪتيون تارا، شمس و قمر،
قربان هزارين مان نه رڳو.
ترجمہ:
دلبر پیارے کر نور نظر
تو سے سرور عالم جن و بشر
تم پر ہیں قربان شمس و قم
کہکشاں ہیں ہزاروں
میں ہی کیا
Bayaan-ul-Arifeen
تعارف
بیان العارفین و تنبیہ الغافلین سید عبدالکریم شاہ بُلڑی والے کی ملفوظات
باسمہ تعالیٰ
سنہ۱۹۳۷ء میں ڈاکٹر دائود پوٹو مرحوم کتاب بیان العارفین میں شامل سندھی ابیات اور ان کی معنیٰ اور تشریح کو شایع کیا اور اس کتاب کی اشاعت سے "بیان العارفین" کا نام بہت مشھور ہوا۔ مگر نام کی مشھوری کے سوا، اس کتاب کی قیمتی مواد کی اہمیت اور شاھ عبدالکریم کی عظمت سامنے نہ آسکی، اُس کی تلافی اب ہو رہی ہے جو کتاب بیان العارفین پہلی مرتبہ مکمل طور پر صحیح سندھی ترجمی کی صورت میں شایع ہو رہا ہے، کتاب کی اصل فارسی متن کا عکس بھی آخرمیں شامل کیا گیا ہے تاکے کوئی محقق ترجمہ کی اصل متن کہ دیکھ کر اطمینان کر سکے ۔
اصل فارسی کتاب کی طرف متوجہ ہونا، اُن کی اھمیت محسوس کرنا، اور ان کے سندھی ترجمے کا اِرادہ کرنے کا سارا سھرہ محترم ڈاکٹر عبدالغفار سومرو کو جاتا ہے جس کی انتھک محنت کے نتیجے کے طور پر یہ اہم کتاب روان سندھی ترجمے کی صورت میں شایع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سومرو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے فکر و فہم پرک خاطر خواہ تحقیق کر کے، سندہ یونیورسٹی سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اور اِس کامیابی نے ان کے لیئےعلمی تحقیق کے طور طریقی اور اعلیٰ فکر و فلسفہ کے تجزئیے کی راہ روشن کی۔ اپنی اعلیٰ صلاحیت کی مدد سے موصوف نے، بیان العارفین کے سندھی ترجمہ اور میون شاہ کریم کے صوفیانہ فکر کو اعلیٰ معیار کے مطابق قارئین کے سامنے پیش کیاہے۔
کتاب کا مقدمہ ڈاکٹر موصوف کے اعلیٰ تنقیدی اور تشریح اور بصیرت کی گواہ ہے ۔اس میں زیربحث آنے والے تمام ذیلی موضوعات بڑی معلومات والے ہیں۔ مگر ان میں سے دو خاص اھمیت رکھتے ہیں: ایک بیان العارفین میں صوفی فکر اور ان کے ماخذات" اور دوسرا "شاھ کریم کا عرفان" پہلے میں سندھ میں صوفیانہ فکر کا تاریخی پس منظر اُجاگر ہو رہا ہے اور دوسرے میں سے صوفیانہ فکر کا روح روشن ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے سندھ میں صوفیانہ فکر کی تاریخ اور ترویج میں یہ مقدمہ ایک دستاویزی حیثیت رکھتا ہے اس کے ساتھ، متن کے آخر میں دیئے گئے تشریحی حوالاجات ، اعلیٰ علمی تحقیق کا عکس ہیں، جن کے مطالعے سے پڑھنے والوں کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔
اِس کتاب کے شایع ہونے سے، پہلی بار میون شاہ کریم کے ذاتی اور فکری عظمت کا صحیح اندازہ ہوتاہے یہ عظمت آج سے چار سئو سال پہلے والی سندھ کے مثالی فرد کی ہے۔ جو اُسی وقت کے بڑے عیال والے والد ہیں :ذریعہ معاش کے لیئے کھتی باری کرنے والے ھاری،غریبوں کا ھمدرد اور حال بھائی نظر آتے ہیں۔ مظلوموں کا مددگار اور اُن کے لیئےاھلِ اِقتدار کے پاس حق کی سفارشات کرنے والے صالحین کے لیئے دینی اور روحانی رھبر اور مرشد، : سالکانِ طریقت کے لیئے صوفیانہ فکر کا شارح ہے: اور ذاتی طور پر صوفی باصفا والی عملی زندگی گذارنے والے عارف با عمل تھے۔
معاصرانہ روایت [ص 43] مطابق شاہ عبدالکریم فقط قرآن شریف کے دو پارے پڑے تھے باوجود اِس کے ، اُن کے ملفوظات اور توضیحات میں، عربی اور فارسی عبارتن اور تصوف کے اھم کتابی ماخذات کی اعلیٰ معلومات کے مثالیں موجود ہیں۔ بیشک یہ اُن کی ایک ذاتی صلاحیت اور افضلیت کا معجزہ تھا، لیکن اُس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اُ س وقت سندہ میں شروعاتی مکتبی تعلیم معیاری تھی۔ اور باھر والا ماحول بھی بڑا فیض والا تھا۔
بیان العارفین میں میون شاہ کریم کے ہمعصر درویش اور اس سے پیشرو عارفوں کے متعلق کافی مواد موجود ہے۔ جس کے مطالعے سے اُس دور کے معاصرانہ ماحول کی پہچان ہو سکتی ہے۔ میون شاہ کریم کی زبان جن بزرگوں اور مقامات کے نام بیان ہوئے ہیں۔ اُن کے متعلق مزید معلومات مھیا کرنے سے اُس تحقیقی کا دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے مثلن شاہ عبداللطیف بھٹائی کے رسالے اور سوانح پر تحقیق کرتے راقم کو " بیان العارفین" میں شامل کچھ ناموں کے متعلق مندرجہ ذیل مقامات ملے ہیں۔
- حسین گاڈر {ص 125} گاڈر فقیر کا مقام، میرپور بھٹورو سے 12 میل جنوب مشرق کی طرف گونگڑو کے پاس ہے جہاں سالانہ میلا لگتا ہے
- پیر لاکہو {ص 368} جاتی کی طرف ہے۔
- سید جعفر{ص 19}بڈھو ٹالپر شھر کے شمال مغرب کی طرف ہے اور سالانہ میلا لگتا ہے۔
- سید لال شاہ {ص 380} " لال کے نام سے دو مقامات : ایک لال چھتو، رڑی کے جھنگلات شمال میں ہے دوسرا لال محمودانی، میاں حسن علی سے مشرق کی طرف جہاں میلا لگتا ہے۔
- لدھو فقیر {ص 292}،یہ شیخ لدھو فقیر میر پور بٹھورو سے ۸میل کے فاصلے پر جنوب-مغرب کی طرف جاڑیجو قبیلےکا گوٹھ ہے جو میرپور بٹھورو سے ۳ میل شمال کی طرف "بگو شیر" کا مقام ہے جہاں شاہ کریم نے چلہ کاٹا تھا۔
- دُبی گوٹھ {294}، کھور واھ سے مشرق کی طرف ۱۲ میل کے فاصلے پر دیھ داسڑکی میں ہے جہاں دُبی والے داسڑے رہتے ہیں
- ڈنڈی {ص ۳۱۵}اور ڈاڈون {ص ص ۳۶۰،۲۰}دونوں گائوں ٹنڈو محمد خان سے بلڑی شاہ کریم کی طرف جانے والے شاہراہ پر دائیں طرف موجود ہیں۔
- رادھن گوٹھ {ص ۳۳۱}= رادھوڑی گوٹھ جو بُلڑی سے ۴ میل شمال کی طرف ہے۔
- راہوٹ {ص ص۱۳۸،۳۱۵} بَنو شہر سے ۲ میل مشرق کی طرف موجود ہے۔
- لنڈان {ص ۳۳۱}غالبا ماتلی سے شمال مشرق کی طرف جہاں دیھ لنڈانا ہے
- کاتیار گوٹھ {ص ۳۰۲،۳۷۹}بُلڑی سے شمال کی طرف کاتیاروں کے تیں گائوں ہیں جہنگ کاتیار، مُلا کاتیار عبدالرحیم کاتیار ۔
- گوٹھ مناھیجی {ص ۳۱۳} یہ گائوں کھور واہ سے ۱۵ میل جنوب مشرق کی طرف ہے "مناھین جت قبیلے کی ایک شاخ ہے جو شاہ کریم کے مرید ہیں"۔
- ھٹڑی{ص ص ۳۰۸،۳۳۴} بٹھورو سے ۴ میل شمال کی طرف جہاں ریت کے ٹیلے ہیں۔
اوپر دیئے گئے تمام گائوں سب کے سب بُلڑی کے آسپاس ہیں جن کی پہچان سے میوں شاہ کریم کے آمدورفت والے قریبی علائقے کا نقشہ نمایاں ہے۔ زیادہ اہم تحقیق اس بزرگوں کے گائوں اور باتوں کی مزید معلومات سے ہوگی۔ جن کے نام بیان العارفین میں آئے ہیں کتاب کا عالمانہ مقدمہ ایسی تحقیقی مطالعے کا دروازہ کھولتا ہے۔
اِس کتاب کی شروعاتی تیاری، کمپوزنگ اور بٹر پیپر کے مرحلوں تک"علامہ قاضی رسالے کے منصوبے اور اشاعت "کے امداد سے ہوتی ہے۔ کتاب کی چھپائی کےاخراجاتحکومت سندہ کے محکمہ اوقاف کے دی ہوئی گرانٹ سے مکمل ہوئی۔ جس کے لیئے محترم شیخ قبول احمد، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف سندہ کا تعاون شاملِ حال رہا۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ شاھ عبداللطیف کے رسالے کی نایاب پہلی بمبئی ایڈیشن کے اشاعت کے بعد یہ دوسرا اھم کتاب ہے، جو حکومت سندہ کے محکمہ اوقاف اور علامہ آئی آئی قاضی چیئر کے مشترکہ کوشش سے شایع ہو رہا ہے۔
دستخط
{ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ}
چیئرمین علامہ آئی آئی قاضی چیئر
سندھ یونیورسٹی اولڈ کئمپس
حیدر آباد سندھ
- ذوالحج ۱۴۲۲ھ
- ۲۸ فیبروری ۲۰۰۲
پیشِ لفظ
شاہ عبداللطیف بہٹائی کے متعلق مشہور روایت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ قرآن پاک کے علاوہ مثنوی رومی اور شاہ عبدالکریم بُلڑی والے کے ملفوظات "بیان العارفین" اپنے پاس رکہتے تھے ۔ اُسی حقیقت کو مدَے نظر رکہتے جب میں نے شاہ عبداللطیف کے فکر پر ڈاکٹریٹ کے لیئے مقالہ بعنوان "شاہ عبداللطیف کا صوفیانہ فکر اور مولانا رومی" پر تحقیق کا آغاز کیا، تو میں نے انہی کتابوں کو بنیادی ماخذ کی حیثیت سے سامنے رکہا۔ مولانا رومی کے مثنوی فارسی کے علاوہ دنیا کی ہر مُہذِب زبان میں دستیاب ہے۔لیکن سوال یہ ہے کہ بیان العارفین جو ابھی تک قلمی صورت میں ہے، وہ کہاں سے ملے؟ کافی وقت تک میں نے اپنا مطالعہ علامہ دآئود پوٹو کی " شاہ عبدالکریم بلڑی وارے جو کلام" تک محدود رکہا۔ جو اُس نے سال 1938ء میں بیان العارفین کے تین قلمی نسخوں کا تقابلُی مطالعہ کر کے اِس کتاب کو مُرتب کیا تھا۔ اور اُس نے خود لکھا ہے کہ اُنہوں نے ساری توجہ شاہ کریم کے ابیات کے صحیح متن پڑھنے پر قائم رکہی تھی۔لیکن اُس کے ساتھ خود بیان العارفین میں سے کچھ ملفوظات جو اُس نے ابیات کے ساتھ مُناسبت رکہتے تہے۔ اس کا انتخاب ترجمہ کر کے شامل کرنے پر اکتفا کیا۔ اِس کتاب کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن سال 1958ء میں دوبارہ شایع ہوا۔ آخری مرتبہ یہ کتاب بِھٹ شاہ ثقافتی مرکز کے طرف سے سال 1977ء میں شایع ہوئی۔
علامہ دائود پوٹے کے بعد " کریم جو کلام" کچھ مزید تحقیق سے سال 1963ء میں میمن عبدالمجید سندھی نے سکہر سے شایع کروایا۔ میمن صاحب نے اُس کے بعد بیان العارفین کے منظوم سندھی ترجمہ جو "کاٹھ بانبھن" نے سنہ 1213ھ میں مکمل کیا تھا جس کو موضوع بنا کے سندہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اور اُسی تحقیق کے آئینے میں " کریم جو کلام" سندھی اکیڈمی لاڑکاںہ کی طرف سے سال 1976ء میں نئے سرے سے مُرتب کر کے شایع کروایا۔ نئی تحقیق کے دوران میمن صاحب نے ایک سے زیادہ قلمی نسخوں کو پیشِ نظر رکھا اور اُس لیئے انہوں نے اپنی اِس نئی کتاب میں پہلے سے زیادہ مواد شامل کیا۔ لیکن پھر بھی بیان العارفین کا مکمل مواد سندھی میں نہ لاسکے اور نہ ہی اُس کا کوئی سبب بیان کیا اِس صورت میں یہ بات میرے لیئے مزید اشتیاق کا سبب بنی کے اصل کتاب کو ضرور دیکھنا چاہئےکہ اُس میں کس طرح کا مواد شامل ہے با الاخر میمن صاحب کے لکھے ہوئے مقدمے کی نشاندھی پر ہم نے وہ قلمی نسخہ حاصل کرلیا جو اُس کے زیِرےمطالعہ رہا تھا یہ قلمی نسخہ منصورہ لئبریری کی ملکیت تھا جو سال ۱۲۴۳ھ میں کاتِب محمد صالح نے لکھا تھا اُسی نسخے کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ علامہ دائود پوٹو نے یا میمن عبدالمجید سندھی نے اصل کتاب کا چوتھا یا پانچھوا حصہ بھی سندھی میں مُشکل سے منتقل کیا تھا کیونکہ اُنکی ساری توجہ شاہ عبدالکریم کے کلام کو صحیح صورت میں مُرتب کرنا تھا۔
بحرحال ہمارا موضوع شاہ عبداللطیف کے فکر کو شاہ کریم کے حوالے سے سمجھنے اور اُن کی تشریح کرنا تھا، جس کے لیئے شاہ کریم کے ابیات کے سِوا اُس دوسرے مواد کا مطالعہ بھی بیحد ضروری تھا۔ بیان العارفین کے سَرسَری مطالعے سے معلوم ہوا کے اُن میں واقعی تصوف کی بنیادی تصورات کی تشریح موجود ہے اور اُس میں سے شاہ کریم کی فکر اور عرفان کو اچھے طریقے سے تشریح کیا جا سکتا ہے اِس کے علاوہ یہ کتاب سندہ کے تصوف کی ارتقا کی اھم کڑی ہے۔جِس میں شاہ لطیف کی فکری ارتقا اور تصوف کو سمجھنے میں بڑی مدد مل سکے گی۔
بیان العارفین پر یہ تحقیق چل رھی تھی کہ اُس کتاب کا نھایت معتبر اور صحیح نسخہ سید علی میر شاہ {جونو گوٹھ ضلع بدین} کے پاس ہے۔ شاہ صاحب ذاتی دوستی اور علمی ذوق سبب یہ نسخہ کچھ وقت کے لئے ہمارے حوالے کرنا قبول کیا۔یہ نسخہ ۱۲۲۸ھ میں ضیاالدین بِن گل محمد تاریخ ۲۹ رمضان المبارک میں لکھ کر پورا کیا۔ کتاب کے آخر میں شاہ کریم کا خاندانی شجرہ اور سلسلہ بھی شامل ہے ورق گردانی سے معلوم ہوا کہ یہ نسخہ واقعی بھترین اور نہایت خوش خط لکھا ہوا ہے جو منصورہ والے کے پاس ۱۵ سال پہلے لکھا پڑا تھا، اُسی جستجو کے دوران ایک تیسرا قلمی نسخہ قمبر کے راشدی خاندان محترم صفی اللہ عباسی کی معرفت سے مِلا۔ لیکن اُس کی شروعات میں اُس کے کافی صفحات ضایع شدہ تھےاور پھر بھی آخر میں نامکمل تھا اُسی وجہ سے اوپر کتابت وغیرہ کا بھی کوئی سال لکھا ہوا نہیں تھا بھرالحال اُن تینوں نسخوں میں سید علی میر شاہ والا نسخہ نہایت عمدہ اور ھر لحاظ سے بھتر ہے۔
جب یہ ساری حقیقت میں نے سندھ کے نامور ادیب اور عالم شاہ عبداللطیف کے فاضل اور محقق ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کو کہا تو اُس نے بھی اُس کی ضرورت کو شدت محسوس کروایا اور کہا کہ بیان العارفین کا مکمل سندھی ترجمہ شایع ہونا چاہیئے، بلکہ یہ اُس سے پہلے "شاہ جو رسالو" کے ماخذ تیار کرنا چاہتے تھے ۔ مزید اِس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اِس کتاب کی غیر معمولی اھمیت سبب اصل فارسی متن کو بھی سندھی ترجمی کے ساتھ شایع کیا جائے، تاکہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیئےمحفوظ ہو سکےپہلے یہ کام محترم صفع اللہ کے حوالے سے کوشش کی گئی لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کِن مجبوری سے اِس کام کو انجام نہ دے سکا ، اِس صورت میں یہ کام میں نے سر انجام دیاشاید اِ س لیئے کہ اِ س سارے کام کی تحریک مجھ سے شروع ہوئی تھی، تاھم مجھے اپنی فارسی دانی پر اِتنا اعتماد نہیں تھا، مگر شاید یہ سب کچھ غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔
اِس سلسلہ میں دوسری نھایت اہم کتاب جس میں سے ترجمہ ،مقامات، خاندان اور آدمیوں کے نام سمجھنے میں مدد مل سکے، یہ بیان العارفین کا پُرانی سندھی میں منظوم ترجمہ تھا، جو عبدالرحمان بن محمد ملوک کاٹھ بانبہن نے سن 1213 ھ میں مکمل کیا آگے چل کر وہ ہی ترجمہ 1293 ھجری میں مخدوم عبدالصمد نورنگ پوٹو نے مطبع مرغوب ھر دیار بمبئی سے چھپوا کر منظرے عام پر لائے۔ یہ کتاب علامہ دائود پوٹو نے شاہ کریم کے کلام مُرتب کرںے وقت استعمال کیا۔ ہم نے بھی اِس کتاب سے اِستفاد حاصل کیا۔ مگر اِن میں سے کچھ مقامات پر کچھ نقول چھوڑی گئی ہیں، جیسے کہ کہیں کہیں پر تھوڑا بہت اضافہ کیا جا سکے، اِس طرح اِس میں سے کچھ ابیات غائب ہیں۔ یہ ھی سبب ہے کہ ہم نے سارا دارومدار سیدعلی میر شاہ صاحب والے نسخے پر رکھاہے، جو ھر لحا ظ سے معیاری ہے اور اُس کے لیئے اُس کے اصل فارسی نسخے کا عکس اُس کے ساتھ چھاپ دیا گیا ہے، منصورہ والا نسخہ بھی کئی جگہوں پر ناقص تھا اِس لیئے، اُس کی اختلافی مواد کو نظر انداز کیا گیا، جو ویسے بھی بہت کم ہے، البتہ کہ عکسی کتاب کے آخر میں منصورہ والے قلمی نسخے میں شاہ عبدالکریم کے خاندان سے لیکر شاہ عبدالطیف تک، فاضل مؤلف نے ۴۶۷ اشعاروں پر مشتمل جو کہ منظومِ احوال دیا گیا ہے، اُس کا عکس بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اِس مواد کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔
آخر میں اُن تمام احباب کا میں دل کے گہرایوں سے متشکر ہوں جنہوں نے اِس کام میں میری مدد کی، اور اِس تاریخی کام کو سر انجام تک پہنچانے میں ہمت افزائی کی ۔اُس میں خاص طور پر ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، صدر علامہ آئی آئی قاضی میموریل سوسائٹی جس کتاب کو مسودے کی نظر سے نکالا اور وقت بہ وقت رھنمائی کی۔ یہاں پر اِس بات کا ذکر کرنا بھی لازمی ہوگا کہ اِس کتاب کی شروعاتی مرحلوں میں علامہ قاضی سوسائٹی کا تعاون حاصل رہا۔ جناب سید علی میر شاہ صاحب نے اپنے خاندان کی طرف سے بیان العارفین کا نسخہ دے کہ اِس کام کو مکمل کرنے کا موقعہ دیا۔ قاضی شوکت علی (پُرانہ ھالا والے ) اور برادرم سلیم اللہ صدیقی پاٹائی نے بھی میری خصوصی شکریہ کا مستحکہ ہے جنہوں نے کتبخانے سے مستفید ہونے کا ہر وقت بھرپورموقعہ دیا۔میں سندھ سرکار کے محکمہ اوقاف کے لائق چیف ایڈمنسٹریٹر محترم قبول احمد شیخ کا نھایت شکر گذار ہوں کہ اُس نے کتاب کی اہمیت کی پیشِ نظر محکمہ اوقاف کے تعاون سے اُن کو شایع کرنے کی ذمیداری قبول کی ۔
۱۲-مھمانہ خانہ، عبدالغفار سومرو
پشاور صدر، پاکستان
مورخہ۱-ذولاحج ۱۴۲۲/ بمطابق ۱۳ فیبروری ۲۰۰۲ء
مقدمہ
شاہ کریم کا سوانحی خاکہ
شاہ کریم عبدالکریم ۲۰ شعبان ۹۴۴ھ/ ۱۵۳۸ء کو مٹیاری کے شھر میں پیدا ہوئے اور ۸ ذوالقعد ۱۰۳۲ھ/ ۱۶۲۳ء کو اپنے گائوں بُلڑی میں وفات پائی، موجودہ کتاب " بیان العارفین" کے خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک شاہ کریم کی فاضل معتقد محمد رضا بن عبدالواسع داروغہ گھر جو ٹھٹہ کےرہنے والے تھے، جس نے شاہ کریم کی وفات کے چھ سال کے بعد یعنے ۱۰۳۸ھ/ ۱۶۲۹ء میں لکھ کر کتاب مکمل کی ۔ اِس لحاظ سے یہ ایک انتھائی مستند تذکرہ ہے، اِس کتاب میں شاہ کریم کے خاندان کا مختصر اور زندگی کا مفصل احوال دیا ہوا ہے، اُس کے ساتھ تعلیمات اور ھدایتوں، صوفیانہ اقوال اور عارفانہ اقوال اپنے مریدوں کے سامنے یا دوسرے بزرگوں سے ملاقاتوں یا مجلسوں میں ارشاد فرمایا شامل ہیں اُس کے سوا شاہ کریم کا شجرہ نسب اور سلسلہ طریقت بھی دیئے گئے ہیں کتاب کے آخر میں شاہ کریم کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاہ کریم کے آٹھ بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ شاہ کریم کی وفات کے بعد چوتھا بیٹا میاں دین محمد گادی نشین ہوا۔ اور دوسرا بیٹا جلال شاہ کی چوتھی پُشت میں سے سندھ کا عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی پیدا ہوا۔
بیان العارفین میں شاہ کریم کی زندگی متعلق جن باتوں کا پتہ چل رہا ہے وہ مندرجہ ذیل دی گئی ہیں
(الف) شاہ کریم کی تربیت اُس کی والدہ نے کی کیونکہ وہ ابھی چھوٹا تھا کہ اُس کا والد وفات پاگیا
(ب) شاہ کریم بچپن کے ہی عمر میں شروعاتی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔
(ج) شاہ کریم بچپن ہی سے اپنی طبعیت میں سماع کی طرف مائل تھے، جب کہ وہ پڑھائی چھوڑ کہ سماع میں شریک ہوتے تھے۔
(د) جوانی میں وہ خود بھی حصہ لیتا تھا، ایک دن ایسی ہی محفل میں مشغول تھے کہ اُس کے بڑے بہائی اُنہیں وہاں سے لیکر قاضی کے سامنے لاکر پیش کیا، اور اُن کی نکاح پڑھائی گئی۔
(ھ) جب تک سید جلال زندہ تھے تب تک شاہ کریم گھر یلو ذمیداریوں سے آزاد تھے اور زیادہ وقت سماع اور ذکر کی محفلوں میں گذارتے تھے۔
(و) ایک، دو، حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سیر اور سفر کیا وہ گجرات کے شھر احمد اباد تک جا چکے تھے اور وہاں پر بھی وہ سماع اور ذکر کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور وہاں پر ہی اُس نے ھندی میں شاعری سنی، جن میں سے کئی بیان العارفین میں شامل کیئے گئے ہیں،
(ز) شاہ کریم محنت مشقت اور سخت مزدوری والی زندگی گذاری۔ اپنی کھیتی باڑی خود کرتے تھے، بلکہ گھر کا کام کاج بھی خود کرتے تھے، اتنا بہی مذکور ہے کہ وہ اپنے گھروالوں اور بچوں کے لیئے کبھی کبھار چاول وغیرہ بھی پکایا کرتے تھے۔
(ح) جبکہ شادی کے بارے میں صوفیوں کا نظریا کسی حد تک غیر رِواجی رہا ہے، لیکن شاہ کریم کی شادی کے بارے میں خیالات زیادہ سخت اور منفرد تہے۔
(ط) شاہ کریم صوفیوں کی طرح معمول کے مطابق عبادت کے علاوہ سخت ریاضتیں بھی کیں، اِس کتاب میں اس سلسلے میں نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ شاہ کریم اپنے دن اور رات کس طرح اور کونسی مشغولیات میں گذارتے تھے۔
(ی) انہیں سماع سے فطری اور غیر معمولی لگاؤ تھا، اس قدر کہ جب کہیں قوال یا ذاکر کے علاوہ کوئی اعلیٰ معنیٰ اور فھم و الا شعر سنتےتھے تو اُن پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور اکثر طور پر اپنے اوپر رکھی ہوئی چادر انعام کے طور پر دے کےپھر محفل سے اٹھتے تھے مطلب کہ کبھی بھی کسی قوال کو خالی ھاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔
(ق) شاہ کریم اسلام کے اوائلی صوفیائے کرام کے زھد اور تقوا کی اعلیٰ مثال تھے۔
کم بولنے، کم کھانے، اور کم بات کرنے والے اصول کے عملی نمونہ تھے اور اُن کی زندگی اعلیٰ انسانی اخلاق اور ادرش کا مثال تھی۔ اپ بغیر کسی دعویٰ کے پیغمبرِ اسلام کی زندگی کی عملی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اپ بہت سادہ کہاتے تھے،اکثر دن روزے اور فاقے میں گذارتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے گھرمیں کھانے کے لیئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مگر عین وقت اگر کوئی سائل اکر کچھ مانگتا تھا تو خود کو تو چھوڑدیں، گھروالوں کو بھی بھوکہ رکھ کے سائل کی مدد کرتے تھے۔
(ل) شاہ کریم کا زمانہ ارغونوں اور تُرخانوں کے ظالمانہ جبر و استبداد کا زمانہ تھا، مگر جب بھی کوئی ستایا ہوا مظلوم اپ کے دروازے پر اتا تھا، تو خود اُن کی دادرسی کے لیئے اُس کے ھمراہ حکمرانوں کے ایوانوں تک چلے جاتے تھے اور کبھی کام ہوتا تو اور کبھی نہیں بھی ہوتاتھا۔اِس سلسلے میں اپ اُس شخص کے پاس بھی بار بار جانے سے نہیں کتراتے تھے، جس نے پہلے کام کرنے سے نٹانے کی کوشش کی تھی۔ اپ اِس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔
(م) شاہ کریم کے اُس وقت کے عالموں اور بزرگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور خاص طور پر مخدوم نوحؒ سے بڑی عقیدت تھی۔ بیان العارفین کے مطابق ہر چند کے بظاھر سلطان ابراھیم بھاری سے قادری طریقے سے ذکر کی تلقین کی تھی، مگر اصل میں شاہ کریم اویسی سلسلے کے بزرگ تھے، جیساکے شاہ لطیف کی سوانح نگار میر سانگی خود اس نے لکھا ہے کہ شاہ کریم سے لیکر شاہ لطیف تک یہ خاندان قادری سلسلے سے منسلک رہے، تاہم شاہ لطیف نےخود اویسی سلسلے کو پسند کیا، جو بات اُن کی مخدوم محمد معین ٹھٹوی کے ساتھ خط و کتابت میں ظاھر ہوتی ہے۔
مجموعی طورپر ، بیان العارفین میں سے یہ تاثر ملتا ہےکہ شاہ کریم نے بھرپور عملی زندگی گذاری، جس میں انسانی ھمدردی، اور اعلیٰ اخلاق کے کئی مثالیں موجود ہیں، بلکہ اُن کی زندگی میں تصوف متعلق اُس عام منفی رائے کی تردید ہوتی ہے، جس کے مطابق صوفیوں کو مور د الزام ٹھرایاجاتا رہا ہے کہ وہ عمل کی دنیا سے فرار ہو کر خانقاہوں میں پناہ لیتے ہیں اور دوسروں کے مال پر گذر سفر کرتے ہیں۔ بیان العارفین میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاہ کریم کبھی بھی اپنی طرف سے قرامت دکھانے کی دعویٰ نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا تاثِر دینے کی کوشش کی ۔ مطلب کہ تصوف کے اصول کسی بھی مرحلے میں اس کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہ بنیے۔ نہ فقط خود اُس پر عمل کر دکھایابلکہ دوسروں کو بھی ایسی تلقین کرتے رہےکہ انسان کا عمل اور کردار ہِ اُس کی اصل قدر اور پہچان ہے۔
شاہ کریم کی سماع کی روایت
صوفی ادب اور تذکروں میں سماع اور ذکر کا شروع سے بیان ملتاہے صوفیوں کی اولین تصنیفات ابونصر سراج کی کتاب (اللمع 378ھ)، ابو طالب مکی کے (قوت القلوب، ۲۸۲ھ)، کلاباذی کا کتاب (التعرف" ۳۸۰ھ)، ھجویری کا کشف (المحجوب ۴۶۵ھ)، قشیری کا رسالہ (قشیریہ ۴۶۵ھ)، اور امام غزالی کا احیا علوم الدین شامل ہیں۔ اسی طرح ساتویں صدی ھجری یا پھر ۱۳ویں صدی عیسوی میں لکھا ہوا، شیخ الشھادب الدین کی سھروردی کے عوارف المعارف سماع پر بھی پورا باب موجود ہے، برصغیر یا پاک و ھند میں سب سے پہلے چشتی سلسلے میں بزرگوں کے پاس اور اُس کے بعد سھروردیوں کے پاس سماع کو اھم حیثیت حاصل رہئی ہے۔ اِن تمام تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی صوفیائے کرام کبھی کبھی سماع کے دوران جذب اور محبت کے غلبے کے سبب اِس فانی دنیا کو چھوڑ کے واصل بااللہ ہوگئے ھجویری کشف المحجوب میں اپنا انکھوں دیکھا ایک ایساواقعہ بیاں کیا ہے۔
چشتی سلسلے کہ مشھور بزرگ بختیار کاکی کے لیئے مستند روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ شعر سنا اُن پر ایسا حال تاری ہو گیا جو تین دن کے بعد اُس حال میں فوت ہوگئے
کشتگان خنجر تسلیم را،
ھر زمان از غیب جانی دیگر است
ترجمہ: تسلیم کی چھری سے کٹے ہوئے کو ھر گھڑی میں غیب کی طرف سے ایک نئیں زندگی ملتی ہے شیخ (بھاؤالدین زکریا مُلتانی ۶۶۱ھ) کے لیئے مشھور ہے کہ وہ سماع سنتے تھے، روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ رومی کے قوال کے نام سے ایک ادمی ملتان ایا ، شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کے راگ شیخ الشیوخ شھاب الدین سھروردی بھی شوق سے سنتے تھے، یہ سن کر شیخ نے فرمایا کہ پھر تو زکریا بھی راگ یہ ضرور سنے گا، قوال نے عشا کی نماز کے بعد راگ شروع کیا جس میں یہ بند بار بار دہرایا۔
مستان کہ شراب ناب خوردند ، از پھلوئی خود کباب خوردند
ترجمہ: ان مستوں نے جنہوں نے خالص شراب کو پیئا ہے، اُنہوں نے اپنے ہی جسم کے کسی حصے کو کباب کرکے کھایا ہے۔ سندھی تصوف کی تاریخ میں نویں صدی ھجری یا ۱۵ویں صدی عیسوی میں درویش احمد جو ھالکنڈی کے تھے ایک مرتبہ جب وہ نیروں کوٹ میں سماع کی محفل میں تھے کہ اُنہوں نے جب یہ شعر سنا تو اُن کی روح پرواز کر گئی،
سڏ سڻي پرينءَ جو وانگي جان نه ورن
ڪوه ڪبو کي تن سڄي سڻائي ڳالهڙي.
بیان العارفین سے معلوم ہوتا ہے کہ شاھ کریم کو جوانی سے سماع کی طرف فطری رجھان تھا بلکہ اِس کتاب میں اُس کی زندگی کا پہلا بڑا واقعہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اُن کے بڑے بھائی اکثر اُس کو سماع کی محفلوں سے زبردستی گھر لیکے جایا کرتے تھے اِسی طرح جب اُس کی شادی کی گئی تب بھی وہ سماع کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے اُسے سے پہلے جب وہ سماع کی محفل میں موجود تھا کہ اُس کا بڑا بہائی میاں جلال لیکر انہیں قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا، تاکے اُ ن کی نکاح پڑھائی جائے، سماع سے بیحد لگاؤ اس سے بھی ظاحر ہوتا ہے کہ اپ اخر میں یہ کہتے تھے دوسرے لوگوں نےدنیا کے دوسرے فن اور ھنر سیکھے مگر میں کچھ بھی نہ سیکھ سکا سوائے سماع کے۔ ۱۶ویں صدی کی شروع میں لکھی ہوئی تاریخ معصومی کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں صوفیانہ سماع کا بہت زور تھا۔بھرالحال شاھ کریم کی زندگی میں سماع کی غیر معمولی اہمیت سبب ہی اِس کتاب میں ایک پورا باب سماع پر موجود ہے۔ شاھ کریم سماع کے بڑے قدردان تھے جیسا کے بیان کیا ہوا ہے کہ جب بھی سماع کی محفل ختم ہوتی تھی وہ قوال کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کہ اٹھتے تھے مطلب کے قوال کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ بدن پر صرف ایک قمیض تھی، مگر وہ بھی اُتار کے قوالی کو دے دی، دراصل اِ س کی روایت صوفیوں کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ خود کعب بن زھیر کا قصیدہ بانت سعاد سننے کے بعد اپنی کندھوں پر اُوڑھی ہوئی چادر اُتار کر اِنعام کے طور پر اُن کو دی تھی۔
بیان العارفین کے مصنف موجب شاھ کریم اکثر خود سماع کرتےتھے یا خود سماع میں حصہ لیتے تھے یہ سماع کا شوق ہی تھا کہ اُس کو گجرات اور احمد آباد لیکے گیا۔اور وہاں پر اُس کے ھندی کے دوھون اور ابیات سننے کا اتفاق ہوا، شاہ کریم کے نزدیک سماع کی حیثیت ذکر کی طرح تھی اور یہ کوئی عیب یا کوئی نئیں بات بھی نہ تھی۔ ابو طالب مکی قوت القلوب میں کہتے ہیں کہ سماع ذکر کی صورت ہے بشرطی کہ اُس سے خدا کی طرف رجوع ہو، شاھ کریم کی روایت ہے کہ کتنی مرتبہ ہوا ہوگا جو کسی سماع کے دوران کوئی شعر سننے سے اُن پر حال یا وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آتے تھےتو پھر سماع میں مشغول ہوجاتے تھے، بیان العارفین سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں سماع کو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تصور کیا جا تا تھا لیکن دوسرا بھی قول ہے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی اسان راہ سماع ہے اس لیئے اپ اپنے معتقد مریدوں کو بھی سماع میں حصہ لینے کی ھدایت کرتے تھےاور اُن کو یہ بات ھرگزاچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی مرید سماع کو آدھے میں چھورڑ کر اُٹھ کر چلاجائے اِس سلسلے میں وہ کہتے تھے سماع کے تمام اداب پوری طرح ادا کرو۔بھرالحال سندہ میں صوفیانہ سماع کی روایت جو شاہ کریم کے پاس ملتی ہے اُس سے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے نھایت منظم طریقے سے جاری رکھا۔
حکایات میں حقیقت کا پہلو
عام طور پرسوال پوچھا جا تا ہے کہ تصوف جدید دور کے انسان کے لیئے کس کام کا ہے یہ سوال اُس پس منظر میں پوچھا جاتا ہے کہ صوفیانہ ادب میں ذیادہ تر ایسی حکایت، منقولات اور واقعات بیان کیئے ہوئے ہیں۔ جو عقل سے باہر یا بعید از قیاس سمجھے جاتے ہیں۔ اُس کا ایک سیدہ و صاف جواب یہ ہ کہ خالص عقل کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے والوں کی تعداد کسی بھی دور میں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر رہا ہے یہ ہی سبب ہے کہ دنیا میں سموری مذہبی اور اعلیٰ ادب میں تشریح کا موثر طریقہ تمثیل ، نقلِ نظیر اور کہانیاں رہی ہیں۔
اِسی لیئے یہی صحیح ہے کہ تصوف اور خاص طور پر ملفوظاتی ادب میں واقعی کئی ایسی باتیں ہیں جو طبعی لحاظ سے ناممکن یا عقل سے باھر لگتی ہیں لیکن بغور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اُس میں اکثر باتیں فقط نصیحت کے خاطر بیان کی گئیں ہیں اصل مقصد انسان کی رہنمائی کرنا اور اُسے نیکی اور بدی کی تمیز سے واقف کرنا ہے۔ یا بنیادی سوال نصیحت کا ہے اور اُس کے لیئے مابعد طعیاتی یعنی عقل سے ماورا طریقوں کی ضرورت ہے۔ انسانی تاریخ اور فکر کا مطالعہ جس میں خود مذہب بھی شامل ہے بتاتا ہے کہ یہ کام مابعد طبعیاتی کے طریقے کی بغیر ممکن نہیں۔
اِسی پسِ منظر میں دیکھا جائے تو اوائلی دور کے دیو اور پریوں کی کہانیاں یا جانوروں یا پرندوں کی کہانیاں انسانی نفیسات کے عین مطابق تھیں ۔لیکن جیسے ہی انسان نے فکری اِرتقا کے مراحل طئہ کیئے تو اُس کا موضوع براہ راست انسان خود بن گیا۔یہ بات سب سے صوفیانہ ادب پر صحیح صادق آتی ہے کہ جہاں ہر بات محور انسان کی اپنی ذات اور اُس کا شعور ہے ۔ وہ اُن کی ذات کا شعور ہی ہے جو اُنہیں خدا کی ذا ت کا شعور عطا کرسکتا ہے اِسی لحاظ سے تمام صوفی بزرگوں کا بنیادی اصول " من عرف نفس و فقد عرف رب ھو، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا رہا ہے تمام صوفی ادب خدا شناسی خود شناسی اور انسان شناسی پر مشتمل ہے یہی سبب ہے کہ صوفی ادب میں تمام زور دوسرے انسانوں کے حقوق کی شناس اور ادائگی، اُن سے برتاؤ اور سلوک، انسانوں کے باھمی حقوق اور فرائض، معاشرتی اداب ایک دوسرے سے مساویانا چال چلن اور عزتِ نفس وغیرہ جیسے اعلیٰ انسانی اقدار پر رہا ہے اُس لیئے انہوں نے انسان کی منفی قوتوں غصہ اور غیبت، جھوٹ اور غلط روی تکبر اور ھٹ درھمی اور دیگر ایسی بدعادتوں کو ختم کردیںے کی ترغیب دی ہے اور انسانی شخصیت کے مسبت پہلئوں سچ اور برداشت صبر اور شکر امید اور توکل مساوات اور محبت پر زور دیا ہے حقیقت بھی یہی ہے کے انسانی معاشرے کی بقا اور دوام کے لیئے منفی قوتوں کی مقابلے میں مسبت قوتوں کو روبعمل لانا ضروری ہے۔ صوفیوں کے پورے فلسفے انسان کا انسان سے اور انسان کی کائنات اور خدا سے تعلقات میں وہ ہی بات نظر آئیگی۔ اِس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو صوفیانہ ادب میں جو بھی نقل اور نظیر بیان کیئے گئے ہیں اور ان کا حاصل انسان کی اپنی ذات کی اصلاح ہے جہاں تک جو ملفوظات یا حکایتں یا جو زیادہ تر ولیوں اور بزرگوں کے حوالے سے شامل کی گئیں ہیں وہ اِس لیئے ہیں کہ انسانی نفسیات بڑی شخصیتوں کے حوالے سے اکثر متاثر ہوتی رہئی ہے اور وہی ھستیا ں اصلاح کا سب سے بڑا رویہ رہی ہیں۔ اُنہی کو عوام الناس اپنے لیئے روشنی کا مینار کی حیثیت دیتے ہیں اب جیسا کہ صوفیائے کرام کا مطمعی نظر ھمیشہ نصیحت اور ھدایت تھی اُس لیئے انہوں نے خوام خواہ اُن باتوں کی اصلیت پر زیادہ زور نہیں دیا ہے جس میں اُن کی بالغ نظری شامل ہے اُن کے پاس حکایت یا قصے کی ہیت " Form"" اور ترتیب ثانوی ہے کیونکہ اُن کا اصل مقصد انسانی عمل اور کردار کی اصلاح ہے۔
شاہ کریم کے دور کا سیاسی اور سماجی پس منظر:
سولہویں صدی سندہ کی تاریخ میں انتھائی انتشار اور فساد کی صدی رہئی ہے، جس کی شروعات (۹۲۶ھ/۱۵۲۱ء) میں سندہ کے مقامی سما سلطانوں کو شاہ بیگ ارغون کے ہاتہوں شکست سے ہوئی اور سندہ کے اوپر باھر سے انے والوں کا راج قائم ہوا۔ شاہ بیگ ارغون ابھی اپنے آپ کو اُس حد تک مستحکم نہیں کرسکے تھےجو ۲ سال کے اندر ہی فوت ہوگئے ، مرنے کے بعد اُس کا بیٹا شاہ حسن حکمران ہوا، لیکن ایک بار پھر سما خاندان کے طرف سے جام فیروز بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا مگر بُری طرح ناکام ہوا۔
جبکہ شاہ حسن نے ۳۵ سال حکومت کی، مگر اِس کا دور بھی انتھائی افراتفری اور کشمکش والاثابت ہوا۔ ھمایوں 1540ء میں شیر شاہ سوری سے شکست کہاکے سندھ کی طرف رخ کیا اور تقریبا ۳ سال تک مسلسل سندھ کے اندر بہٹکتے رہئے۔ شاہ حسن سیاسی چال کے طور انہیں کنہیں بھی ارام سے ٹکنے نہیں دیا، جہاں بھی وہ گئے اُدھر اُس کے لیئے مشکلات پیدا کیں۔ آخر کار ھمایوں نے قندھار کا رخ کیا ۔ شاہ حسن ارغون لاولد فوت ہو گئےتو اُن کی بیگم نے مرزا عیسیٰ ترخان سے شادی کی اور اسی طرح وہ سندہ کا حکمران بنا، مگر جب مرزا عیسیٰ حکمران ہوا تو بکھر کے حکمران سلطان محمود نے اُنہیں تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ آخر کار 1555ء میں مرزا عیسیٰ نے بکھر پر حملہ کیا، وہ ابھی بکھر میں ہی تھے کہ پُرتگالیوں نے ٹھٹہ پر حملہ کیا، اور شھر کو آگ لگادی اور بڑے پئمانے پر لوٹ مار کی اور نجانے کئی انسانوں کا قتلِ عام کیا، کہاجاتا ہے کہ اصل میں مرزا عیسیٰ پپرتگالیوں کو سلطان محمود کے خلاف اپنی مدد کے لیئے بُلوایا تھا، لیکن جب اُنہیں ٹھٹہ میں موجود نہیں دیکھا تو مزید انتظار کے بجائے اُنہوں نے انتھائی ذلیل اور کمینگی مظاہرہ کیا، مطلب کہ شاہ حسین کے مرنے کے بعد سندہ دو حصوں میں تقسیم ہوگئی، بکھر سے لیکر سیوھن تک سلطان محمود کی تسلط تھا، جبکہ سیوھن سے ٹھٹے تک مرزا عیسیٰ کا حکم چلتاتھا۔اسی طرح مرزا عیسیٰ ۱۸سال حکمرانی کرتا رہا اور جب ۱۵۶۶ء میں وفات پائی تو اُس کے بیٹے مرزا محمد نے باقی تختِ نشین ہوا، وہ بڑے ظالم اور سفاک ثابت ہوئے، اِس قدر کے اُس کے چھوٹے بھائی اور داماد بھی اُن ے مخالف ہوگئے اور اُن کے بُلانے پر سلطان محمود بکھر سے مرزا باقی پر چڑھائی کر کے ایا، مگر کو ئی بھی فیصلہ نہ ہوسکا۔
وہ ہی زمانہ تھا جب اکبر بادشاہ نے سندہ کو مغل سلطنت کو ملانے کے لیئے سندہ میں لشکر بہیجا، جس کے نتیجے میں شمال سندہ پر سنہ( ۹۸۲ھ/۱۵۷۴ء)میں مغلوں کا قبضہ ہو گیا، ٹھٹے کے حکمران مرزا باقی یہ حال دیکھ کر اکبر بادشاہ سے مصالحت کا رستا اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اپنی بیٹی اکبر بادشاہ کے حرم میں دھلی کو بھجوادی جس کو اُنہوں نے، قبول کرنے سے اِنکار کیا اور وہ واپس آگئی، آخر کار مرزا باقی جیسے پاگل اور ظالم حکمران سے سندہ کی جان خلاصی ہوئی جو سن (۹۹۳ھ/ ۱۵۸۵ء) میں وہ پاگل بن گیا اور تلوار لیکے اپنے آپ کو زخمی کردیا، اور اُسی وجھ سے اُس کی موت واقع ہوئی۔
مرزا باقی کے مرنے کے بعد اُس کے بیٹے مِرزا جانی بیگ حکمران ہوا، وہ بھی اپنے باپ کی طرح ظالم و جابر ثابِت ہوا، پہلے تو اُس نے اپنے باپ کے بدلے خاطر جانے کتنے بےگناہ اِنسانوں کو موت کے گھاٹ اُتروایا، اُن بد اعمالیوں کی وجھ سے وہ اکبر بادشاہ کا اعتماد کہو بیٹھے، جس کی وجہ سے سنہ ۱۰۰۰ھ/ ۱۵۹۱ء میں عبدالرحیم خانخانان اکبر ی لشکر لیکے سندہ میں داخل ہوا، پورے ایک سال کی کشمکش کے بعد مرزا جانی بیگ نے سر جھکایا ، مرزا جانی بیگ کولیکر دھلی میں لے گئے، اور سندہ میں ۱۶ سالوں کے بیٹے مرزا غازی بیگ کو ٹہٹہ کا گورنر مقرر کیا، اِس کے بعد جب تک سندہ مغلوں کی سلطنت میں شامل رہی، تب تک دھلی سے گورنر مقرر ہو تے رھتے تھے۔
مغل صوبیداروں اور اُن کے نائبین کے وقت میں سندہ پر گیا گذری ؟ اِس کی تفصیل ھمعصر " تاریخ شاھجھانی" میں تحریر ہے، جو ۱۰۳۹ سے ۱۰۴۰ھ دوران یوسف میرک نے تصنیف کی ہے، جیساکہ مصنف نے دیباچہ میں خود کو بتایا ہے کہ اُن کی تالیف کا سبب مغلوں کے نائبین کی طرف سے وہ مظالم اور زیادتیاں تھیں، جو انہوں نے ٹھٹہ ، سیوھن، اور بکھر میں سندہ کے عوام سے روا رکھے اور یوسف میرک خود آنکھوں دیکھا شاھد تھا، اِس کے لکھنے کے موجب سندہ میں کسی بھی قسم کا کوئی امن امان نہیں تھا، جس کے لیئے عوام کی ملکیت اور عزت دونوں محفوظ نہیں تہی۔ حکمرانوں نے کھلے عام عوام کی بیعزتی کی اور ناجائز محصولات اور بھتے وصول کیئے، زمینوں میں جب فصل تیار ہوتی تھیں تو سرکار کے لُفنگےاھلکار لوگوں سے ذرعی زمین کی پیداوار پر لگان وصول کرتے تھے، بلکہ جانوروں سمیت تمام مال اُٹھاکے لے جاتے تھے یہاں تک کے زمین اباد کرنے والے زمینداروں اور کسانوں کے لیئے کچھ باقی نہیں بچتا تھا۔
مندرجہ بالا باتوں کی بیان العارفین سےبھی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مغلوں کے کئی جاگیردار ایسے ہوتے تھے جوزمین کو آباد کرنے والوں کسانوں کو پورا حصہ نہیں دیتے تھے، خود شاہ کریم سے ایسے واقعات ہوئے جس میں اُسکے بیٹوں کی مغلوں کے حکمرانوں کے ساتھ لڑائی ہوگئی اور اُس لڑائی جھگڑے میں مغلوں کے سرپھوڑے گئےجس کی شِکایت مِرزا تک پہنچی۔ شاہ کریم نے ٹھٹہ میں اکر سید جلال بن علی شیرازی کو سفارشی کے طور پر انہیں اپنے ساتھ لیکروہاں چلنے کو کہاتاکہ اِس معاملے کو رفعہ دفعہ کیا جائے ، لیکن جب جلال شیرازی نےچلنے سے انکار کیا تو خود اکیلے سر جاکر مرزا جانی بیگ کے پاس حاضر ہوئے،وہاں جب پہنچے تو ان کے لباس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے یہ دیکھ کر مرزا جانی بیگ اتنا متاثر ہوئے کہ اُس نے جاگیردار کی شکایت کو مسترد کرنا پڑا۔ اُسی طرح دیگر طرح کی زیادتیاں بھی عام جام تہیں، اور اِسی لیئے مقامی لوگ شاہ کریم کے پاس آتے تھے اوراُن کو انصاف کے لیئے مغل حکمرانوں کے پاس چلنے کو کہتے تھے اور شاہ صاحب اُن کا کہنا مان کر حکمرانوں کے پاس چلے بھی جاتے تھے۔ اگر پہلی بار پذیرائی نہیں ملتی تھی تو دوسری بار بھی جانے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے ۔
سندہ اور ھند میں ملفوظات کی روایت:-
برصغیر میں علی ھجویری کا کشف المحجوب میں (۱۰۵۷/۶۵۰)تصوف کے بابت پہلی تصنیف ہے، بلکہ فارسی میں بھی یہ تصوف پر پہلی باضابطہ تحریر ہے، کشف المحجوب جس میں تصوف کی بنیادی تصورات کی تشریح دی گئی ہے یہ کس حد تک تذکرہ بھی ہے لیکن یہ ملفوظات میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ ملفوظات ایسی تحریر کو کہا جا تا ہے جس میں کسی ایک صوفی بزرگ کی زندگی اور تعلیمات اور خاطور پر اُن کی گفتگو اور اقوال کے علاوہ اُن کی نصیحتوں اور بہت سی حکایتوں کو اکھٹا کیا جائے، اِس لحاظ سے برصغیر کی سب سے پہلے ملفوظات چشتی سلسلہ کے بزرگان کی تھیں، جس میں سب سے پہلے "انیس الارواح" ہے جو خواجہ عثمان ھارونی کی طرف منسوب ہے اور اُن کے مرتب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری (۶۳۱/۱۲۶۵ بتایا جا تا ہے دوسرے نمبر پر خواجہ معین الدین اجمیری سے منسوب ملفوظات " دلیل العارفین ہے جس کے مرتب قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تیسرے نمبر پر قطب الدین بختیار کاکی (۶۳۳ھ/۱۲۳۴ء) سے منسوب " فوائد السالکین" ہے، جس کے مرتب فرید الدین گنج شکر جو (۳۶۳ھ/۱۲۶۵ء) ہے چوتھے نمبر پر "راحت القلوب" ہے جو گنج شکرکی طرف منصوب ہے اور اُن کے مرتب خواجہ نظام الدین (724ھ/1324ء) اولیا ھے۔ گنج شکر کی طرف ایک اور ملفوظات کی کتاب " اسرالاولیا" بھی منسوب ہے جس کے مُرتب خواجہ بدرالدین اسحاق ہے نظام الدین اولیا کی طرف اور بھی کئی ملفوظات منسوب ہیں فضل الفوائد جو امیر خسرو نے مُرتب کی تھی اور دوسری فوائد الفوائد جو امیر حسن سجزی نے مُرتب کی۔
بھرالحال اُن سب میں زیادہ مفصل مستند اور مقبول فوائد الفواد ہے جس میں کل۱۸۸ مجلسوں کا ذکر قلمبند ہے اور یہ ۱۵ سالوں کے عرصے کے دوران (۷۰۷ھ سے ۷۲۲ھجری) تک نہایت ھی عقیدت سے انہوں نے مُرتب کی اور آخر میں قبولیت کی خاطر مرشد کی خدمت مِن کی۔ پھراٹھاویں صدی ھجری میں چشتی بزرگوں کے متعلق امیر سید خورد کرمانی کا لکھا ہوا تذکرہ " سیرالاولیا" جو اِس نے (۷۷۰ھ/ ۱۳۷۰ ء) کے دوران تصنیف کی تھی، ایک نہایت معتبر اور جامع کتاب ہے کیونکہ یہ مصنف خاندانی طور پر اُن کے سلسلہ سے وابستہ تھے اور خود ایک عالم فاضل شخصیت تھے، اِس تذکرہ میں چشتی صوفیوں کے سلسلے میں سوانح کے ساتھ اُن کی تعلیمات کو نہایت مؤثر اور دلپذیر انداز میں پیش کیا گیا ہے اِس کتاب کہ کچھ ابواب کے عنوانات بیان العارفین سے کس قدر مشترک ہیں اُس کے علاوہ نقل اور اقوال بھی کہ مشترکہ ہیں۔جس کی نشاندھی تشریحی حوالوں میں کی جائے گی امیر خورد، امیر خسرہ کا ھمعصر تھے، اور نظام الدین اولیا کی صحبت کا شرف اُنہیں حاصل تھا، ۱۰ ویں صدی میں دوسرا اہم لکھا ہوا، تذکرہ " شیخ حامد بن فضل اللہ جمالی کا سیر العارفین ہے، جو اُنہوں نے941ھجری1535ء کے دوران لکھ کر مکمل کی، اِس میں چشتی سلسلے کے بزرگوں کے علوہ کچھ ایسے صوفیائے کرام کا ذکر بھی شامل ہے جن کا مصنف، سندہ اور ملتان کے سیر و سفر کے دوران ملیے تھے ۔ اِس سلسلے میں خاص طور پر سندھ میں سمہ دور کی قابل احترام ھستی مخدوم بلال ہے جس کے پاس اُنہوں نے شیخ شھاب الدین کا سھروردی کا عوارف المعارف دیکھا،
گیارہویں صدی کے اغاز میں ایک نھایت ھی اھم تذکرہ " گلزار ابرار" ہے جو غوثوی مانڈوی نے سال ۱۰۱۲/ ۱۶۵۴ سے ۱۰۱۹ھ/ ۱۶۱۰ء کے دوراں تصنیف کیا ہے یہ تذکرہ جیساکہ گجرات میں لکھا گیا ہے اِس لئے سندہ کے بہت سے بزرگوں کا تذکرہ موجود ہے جس میں خاص طور پر قاضی قادن، مخدوم نوح مخدوم بلا اور شیخ عیسیٰ جنداللہ برھانپوری جو اصل میں پاٹ کا رھنے والے تھےقابلے ذکر ہیں غوثی مانڈوی ، شیخ عیسٰی جنداللہ کے بڑے عقیدت مند تھے، اِس لیئے اُس کا اور اُس کے خاندان کے دوسرے افراد کا احوال تفصیل کے ساتھ دیاہے ۔
اِس تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں سماع اور سندھی کافیاں سندہ سے باہر گجرات میں بہت مقبول تھیں اُس سلسلہ میں مصنف خاص طور پر شیخ لاڈ جیو کا ذکر کرتاہے کہ وہ سندہ میں کافیاں گانے کے وجہ سے کتنا مشھور تھا۔اور اُس کے گانے کے انداز میں تاثیر تھا، غوثی قاضی قادن کا احوال سناتے ہوئے اُن کی شاعری کا بھی ذکر کیا ہے بلکہ اُن کے کئی ابیات کا فارسی نثر میں ترجمہ بھی کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں گجرات کے اندر سندھی شعر و شاعر کو کتنی پذیرائی حاصل تھی دراصل یہ وہی دور تھا جب سندہ کے کئی عالم اور بزرگ سندہ سے نقل مکانی کرکے گجرات اور احمد آباد میں رہائش پذیر ہوئے تھے گجرات کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اہلے سندہ کا وہاں اکثر آنا جانا ہو تا تھا خود شاہ کریم خود بھی گجرات اور احمد آباد گئے تھے جہاں انہیں ھندی زبان کے ابیات اور دوھے سننے کا اتفاق ہوا تھا اور کچھ دوھے تو اُسے اتنے پسند تھے جو وہ خود مریدوں کے سامنے اکثر پڑھا کرتے تھے اِس لیئے بیان العارفین کے مصنف نے بھی تین ھندی ابیات نقل کئے ہیں ۔۔
"گلزار ابرار " بیان العارفین سے صرف ۱۸ سال پہلے تصنیف کیا گیا تھا اُسی وجہ سے اُس کے اندر سندھی بزرگوں کے متعلق کچھ رو ایک بلکل بیان العارفین والی بیان شدہ ہیں۔ اِس کے علاوہ گلزارے ابرار اور بیان العارفین کے مصنف کے فکری ماخزات ایک جیسے معلہم ہوے ہیں تشریحی حوالوں میں اُن بانوں کی نشاندھی کی ہوئی ہے جب گجرات میں غوثی مانڈوی گلزارے ابرار تصنیف کہ رہے تحَ تب سندہ کے اندر سید عبدالقادر " حقیقت الاولیا " کے عنوان سے پہلا تذکرہ سن 1016ھ 1607ء میں مکمل کیا تھا ، جس میں انہوں نے سندہ کے 41 بزرگوں کا احوال دیا تھا اور سب سے پہلے شیخ بھاؤالدین زکریا ملتانی سھروندی کا احوال لکھا، حقیقت الاولیا بیان العارفین سے صرف ۲۲ سال پہلے لکھی گئی اُس لیئے اُن دوںوں کتابوں کے اندر بزرگوں کے متعلق ایک جیسی روایات بیان شدہ ہے دوسرا جو تذکرہ لکھا کیا وہ رسالہ قرحیھ ہے جو مخدوم نوح کی سانح اور تعلیمات کے متعلق ہے جس سے مخدوم نوح کے پوتے مخدوم فتح نے سن 1019ھ/ 1610ء میں تالیف کیا تھا، جو مخدوم خاندان کے پاس محفوظ ہے جیسا کہ مخدوم نوح سے شاہ کریم کی بہت عقیدت تھی اُس لحاظ سے اِس رسالے کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ بھرالحال مکدوم نوح کے متعلق دوسرا مفصل تذکرہ " دلیل الذاکریں" شن 1106ھ/ 1694ء میں حاجی پنحور نے مرتب کیا جو مخدوم خاندان کے مرید اور عقیدت مند تھے، ظاھر ہے کہ یہ ملفوظات بیان العارفین سے بہت بعد کہ ہیں بڑی بات یہ ہے کہ مصنف کے پاس بیان العارفین کا نسخہ بھی موجود تھا جس سے استفاد ہ کرتے اُن میں سے کچھ حکایات نقل کیئے ہیں جو شاہ کریم کے متعلق تھین ، یہ کتاب بھی قلمی صورت میں موجود ہے جس کی فوٹو کاپی جناب قاضی شوکت علی پرانے ھالے والے سے حاصل ہوئی، اور ہم نے تشرحی حوالوں میں اپن باتوں کی نشاندھی کی ہے سندہ کے صوفیائے کرام اور بزرگوں کے سلسلہ میں آخری بڑی کاوش میر علی شیر قانی کی کتابیں اور معیار سالکان طریقتہ ہیں جو انہوں نے بالترتیب 1181ھ/ 1202ھ میں مرتب کیئے تحَ، تحفۃالکرام میں اُنہی بزرگوں کا احوال علاقے کے حساب سے دیا گیا ہے جب کہ دوسری کتاب میں انہوں نے ھر ھجری صدی کے بزرگوں کا تذکرہ ایک کر کے دیا ہے اُس ہوجہ سے یہ قدر تفصیل ہے لیکن دونوں کے اندر مواد تقریباً ایک جیسا ہے معلوم ہوتا ہے کہ " تحفۃ الکرام" لکھتے وقت میر علی شیر فاتح کے سامنے بیان العارفین تھی اُس لیئے انہوں نے ایسے کتاب کے اندر اصول وہی بیان العارفین سے ہو بہو لیا ہے البتہ معیار سالکان طریقۃ میں کن بزرگوں کے متعلق کچھ باتیں نئیں تحریر کی ہیں
بھرالحال میر علی شیر کانع اپنی تحریروں میں بیان العارفین میں صوفی فکر اور اُس کے ماخذ کے طور پر استعمال کیا۔
بیان العارفین میں صوفی فکر اور اُس کے ماخذات سندہ میں تصوف کے اِرتقا کو دو واضح اِداروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شروع والے دور کو اگر اٹھویں صدی ھجری یا ۱۴ صدی تک محدود کیا جائے تو اس میں دُرویشی اور فکر پر بہت زیادہ زور تھا، اور صوفی بزرگ خود بھی اُس کا عملی نمونہ تھا، دوسرے دور میں صوفی فکر و اصل ہو اُس کا آغاز قاضی قادن سے ہوتا ہے اور شاہ کریم میں دو نوں اور افکار سنگم نظرآتا ہے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اِس صوفی فکر کے غلبہ اور ترقی کے کون سے محرکات تھے اور وہ فکر بنیادی طور پا کہاں سے اور کیسے پہنچا۔
بیان العارفین سے معلوم ہو تا ہے کہ شاہ کریم کے زمانہ میں 16 ہیں صدی تک سندہ بزرگ اور صوفیائے کرام اسلامی تصوف کی مثالی شخصیتوں اور اُن کے شاندار کاوش ہے، اچھی طرح یہ خوبی واقف ہو چکی تھی،
تاریخی لحاظ سے ۱۳ویں صدی کے اندر بندہ میں سھفروردی سلسلہ کا زور واضح طور پر نظر آتا ہے سو مرا اور سماع زیادہ تر ملتان کے سھروردی سلسلے سے وابستہ تھے، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سندہ میں سھروردی سلسلہ براہ راست نوح بکری کے ذریعے سندہ میں پہنچا روایت ہے کہ بغداد میں بھاؤالدین زکریا شیخ شھاب الدین سھروردی سے الوداعی ملاقات کرنے لگے تو شیخ نے فرمایا کہ سندہ میں ہمارا ایک ایسے دوست ہیں جو تعل اور دیئے اپنے ساتھ لیکر آتے تھے ہم۹یں ففصل اپنے روشن کرنے کی ضرورت تھیں آپ واپسی میں اُن میں اُن سے ضرور ملیئے گا کہتے ہیں کہ جب بھاؤالدین زکریا اُن سے ملنے کے لئے سندہ آئے تو نوح بکری اُن سے پہلے وفات پا چکے تھے حضرت نوح بکری سکھر میں بکھر کے قلعے میں مدفون ہوئے جو روھڑی اور سکھر کے درمیان دریاہ کے اندر پھاڑ پر واقع ہے اور اُن کا مقبرہ ریلوے لائن سے متصل ہے آج تک موجود ہے 15 ہیں صدی میں شیخ شھاب الدین سھروردی کے نواسے سید محمد مکی جو سندہ اور ھند کے رضوی سادا کے جو امجد ہیں بکھر میں آکر آاد ہوئے جہاں سن 644ھ/ 1248ء صدی میں سندہ کے اندر قادری سلسلے کے کئی بزرگان بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے خاندان کے کئی افراد سندہ میں پہنچ چکے تھے شاہ خیرہ الدین قادری انہیں میں سے پُرانے سے سکھر میں مدفون ہیں سن 911ھ 1507 میں وہ بغداد میں پیدا ہوئے اور 1027 ھجری 1634ھجری میں وفات پاگئے وہ بھی مخدوم نوح کے چھوٹے ھمعصر اور اُن کے عقیدت مند تھے اِس لحاظ سے وہ شاہ کریم کے بھی ھمعصر تھے،
شاہ کریم کا دور سندہ میں فارسی زبان کے عروج کا زمانہ تھا، خاص طور پر ارغوںوں اور ترخانوں کے حکمرانی کے سبب سندہ میں فارسی کا زور تھا، اُس لیئے فطری طور پر سندہ کے تصوف پر فارسی زبان کے عظیم صوفی شعرا مسئلن عطار، رومی، سعدی، جامی کا نھایت واضح اثر ملتا ہے بیان العارفین میں ایک جہ فرفید الدین عطار اور دوسری جگہ شیخ سعدی کا تذکرہ ملتا ہے اور اسی طرھ حکایات کے نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ اُ9ن میں سے کئی عطار کی مشھور کن " تذکرۃ الاولیا" میں کئی بزرگوں کی حکایات ایک جیسے انداز میں بیان شدہ ہیں جن میں شاص طور پر رابع بصری، بایزید نشانی، جنید بغدادی ابراھیم ادھم اور ابوالحسن خارکائی قابلے ذکر ہیں اُس کے علاوہ دوںوں کے اندر جن مشھور اور معروف صوفیوں کا تذکرہ ملتا ہے اُن میں حسن بصری ذونون مصری اور حبیب اجمعی تقیق بلخی منصور بلاج، احمد بلخی خضروی شامل ہیں لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جو "تذکرہ الاولیا" میں نہیں ہیں جس سے ظاھر ہوتا ہے کہ اُس وقت یقیناً کچھ دیگر کتب بھی عروج تھے۔ بیبی رابعہ بصری کاحع پر جانا اور اُس کے استقبال کے لیئے کایعے کا چل کے آنا فقط دو روٹیوں کا آٹا موجود جتھا، جب وہ پکہ کر تیار ہوئیں تو وہ بھی دروازے پر آئے ہوئے کسی سائل کو دے دیں ، جس کے بعد پھر ایک کنیزہ کی روٹیان لیکر آئیں، اِسی طرح بیبی رابعہ بصری کا ھاتھ میں اک اور پانی لیکر نکلنا تاکہ بھشت اور دوزخ کو ختم کر لے اور اللہ کے بندے اُن کی بصیر کسی طفمع کے عطاعت اور عبادت کریں وہ سب منقولات اور دعگر حکایات تذکرے میں موجود ہیں
بایزید کا عرش پر پہنچنا اور وہاں اُس سے خدا کا پتہ معلوم کرنا اور عرش کا جواب دینا کہ اُسے اُن کے بندوں میں تلاش کرنا اُس کے علاوہ کچھ دیگر منقولات بھی تذکرہ میں سے کئے گئے ہیں اُس کے مزید تفصیل اِس کتاب کی آخر میں لکھے گئے ھاترموں میں شستہ کہ ماخذات کی نشاندھی کی گئی ہے اُسی طرح ہم نے بیان العارفین لائی گئی قرآن کی اقوال کی ممکن ماخزات کی نشاندھی اور وضاحت کی ہے بیان العارفین میں عطار کے تذکرہ کے علاوہ جن دیگر کتابوں کی نشاندھی ہو تی ہے وہ منتقل الطھر اور پسند نامہ ہے نہ ایک جگہ یہ عطار کہ اِس شعر کو براہِ راست لانے کے بجائے اُن کا حوالہ دیا گیا ہے،
ڪفر ڪافر روادين ديندار را
ذره دردت دل عطار را.
یہ شعر عطار کی جگہ مشھور کتاب متقل الطھم سے لیا گیا ہے اِسی طرح تجدید و تفرید جو تصوف کے بنیادی اصطلاحات ہیں اور شاہ کریم نے اپنے اِس شعر میں اُن کے غیر معمولی افادیت روشنی ڈالی ہے تجدید اور تفرید کی نھایت عام فھم تشریح عطار نے پندہ نامہ میں دی ہے وہ شعار ھم نے حوالوں میں سمجھانے کی خاطر دیئے ہیں،
جي تجريدان نڱئا، پٺيان ۾ تفريد
هن ڪڏهن ٿئي، هن ڏهاڙي عيد.
تجدید اور تفرید کی تشریح شیخ شھاب الدین سھروردی کی کاب "عوارف المعارف" میں موجود ہے جو بھی سندہ کے صوفیائے کرام نھایت مقبول تھی۔
بیان العارفین میں جو شاہ کریم کا آخری بیت موجود ہے اُس میں ھسن خرکانی کا بہت بڑآ مقام بتا یا گیا ہے اور دعا کی گئی ہے کہ اے معرے مالک جس طرح تو نے اُسے نوازا ہے اُسی طرح ہمارے اُپر بھی اپنی خاص نوازش عطا کی ظاھرہے
خرقان خوش ڪي، اچي ويٺاسون
جئائين ڏنئه حسن کڳ، تئائين ڏيندين تون
کہ اِس یت میں ۱۱ ویں صدی کے مشھور صوفی بزرگ ابوالحسن خارکانی (وفات 424ھجری 1033ء) کا ذکر ہے وہ محمود غزنوی کے زمانے کہ تھے، اور سلطان کی اُس کے ساتھ بڑی عقیدت تھی عطار اپنی مشحور تصنیف " تذکرت الاولیا میں تقریباً 50 صفحات پر اُن کا تذکرہ اور کرامات بیان کئے ہیں۔ اِس شعر سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ کریم کہ ابوالحسن خارکانی کی شخصیت سے بڑا پیار تھا، اِسی وجھ سے تمام صوفیوں میں سے اںہوں نے فقط انہیں کا نام اُس کے شعر میں آیا ہے خرکانی سماع کا بھی ذوق رکھنے والے تھے، " تذکرۃ الاولیا کی روایت کے مطابق حسن خرکانی کی ولادت کی پیشن گوئی بایزید بسطامی ( وفات 260ھجری) نے کی تھی حالانکہ دو۳نوں میں 39 برسوں کا وقفہ ہے اور دونوں شھر قرقان اور بسطام ایک دوسرے سے کچھ ملیلوں کے فاصلے پر ہیں ابوالحسن خرکانی کو بایزید سے بڑی عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کے سبب انہیں اویسی طریقے سے فیض ملا، گویا حسن خرکانی کی فضیلت کا بڑآ سبب اویسی سلسلہ کا ہونا بھی ہے غالباً شاہ کریم کے مندرجہ بالا شعر میں اُسی فیض کی نشاندھی اور ۔۔کی گئی ہے
کچھ صوفی اویسی سلسلہ کو اِس لیئے بلند و بالاسمجھتے ہیں کہ اِس سلسلے میں خدا کی طرف سے براہ رات ففیض یا انعام ملتا ہے شاہ کریم بھی اُسی لئے اپنے آپ کو اویسی سلسلے سے منسوب کرنے کو زیادہ پسند کیا ہے، جب کہ بیان العارفین کے سروع میں ایک روایت شامل ہے جس کے مطابق آپ نے ایک ایسے گمنام شخص کو پیر و مرشد سمجھ کر بڑی خدمت کی جس کا واسطہ بیھار کے علائقے سے تھا، بھرالحال یہ ایک حقیقت ہے کہ سندہ میں ایسی سلسلے کہ بڑے بڑے صوفیائے کرام نے پسن کیا ہے یہی ہے سبب کہ مخدوم نوح کے لیئے بھی اویسی سلسلہ مشحور ہے اور تمام تذکروں میں اِ س بات پر زور ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی پر بھی یہ بات صادق آئی کہ ہے کیونکے شاہ کریم سے لیکر شاہ حبیب تک اُس کا سارا خاندان قادری طریقے سے منسلک بیان کیا جاتا ہے اور اِس کا شجرہ تحریری طور پر ملتا ہے اور جو حقیقت اُن کے ذکر اور فکر کے طریقہ کا سے بھی واضح ہوئی ہے لیکن پھر بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے وقت کے مشھور عالم اور فاضل مخدوم محمد معین ٹھٹوی کو خط لکھ کر اویسی سلسلہ کے مطلق مزید تسلی حاصل کی تھی شاہ لطیف اور مکدوم معین ٹھٹہع کے درمیان کی گئی یہ مُراسلات آج بھی محفوظ ہے دیکھا جائے کہ سندہ تصوف کی قدیم شاعری والی روایات میں صوفیوں کے نام لینے کا بہت کم رواج تھا غالباً یہ شاہ کریم بھی تھے جس نے شاعری میر حسن خرکانی جیسے صوفی بزرگ کا نام لیکر ذکر کیا ہے اور اِسی طرح شاہ لطیف نے منصور حلاج کا نام لیا ہے تذکرہ عطار کے بعد جسے دوسری شخصیت کا بیان العارفین کے مُرتب اور اُس میں شاہ کریم کے فکر پر اثر نظر آتا ہے وہ فارسی اور اُن کے بڑے صوفی شاہ اور نثر نویس مولانا عبدالرحمٰن جامی (817-898ھ) اور اُن کی کتاب (لوایح) ہے اول تہ بیان العارفین کی شر وعات نبی کریم ﷺ کہ جس قول:
اُسی قول سے کی گئی ہے آغاز ہوی قول لوایح کے بلکل آغاز ہھی قول موجود ہے بلکہ لوایح میں کچھ مزید الفاظ بھی ہیں اُس کے بعد توحید اور اُن کی تشریح والی بات میں تحت وحدت الوجود کو جس انداز میں سمجھایا گیا ہے اور فارسی اشعار حوالے کے طور پر دیئے گئے ہیں وہ لوایح میں سے ہیں مثال کے طور پر صفحہ نمبر 147 مندرجہ ذیل اشعار موجود ہیں
زد خنده که من بعکس خوبان جهان
در پرده عيان باشم ص بي پرده نهان
دراصل یہ دونوں سطور لوایح 15کی رباعی میں سےلی گئیں ہیں، مکمل رباعی اِس طرح ہے:
با گلرخ خویش گفتم ای غنچہ دھان
ھر لخطہ مپوش چھرہ چون عشوہ گران
زد خندہ کہ من بعکس خوبان جھان
درپردہ عیان باشم و بی پردہ نھان
ترجمہ: میں نے گلابی چہرہ رکھنے والے محبوب کو کہا:لوایح جامی تصوف اور سلوک میں فکری لحاظ سے صفحہ اول کی کتاب ہے جس میں خواجہ عبداللہ اور انصاری، ابن عربی صدر اللدین ۔۔۔، مولانا رومی، اور محمود شبستری کے حوالے ملتے ہیں تصوف کے بنیادی مسائل مثلاً خدا اور انسان کا تعلق وجود اور آدم فنا اور فکر کو عقلع اور فلسفانہ انداز میں وضاحت کی گئی ہے مسئلن فنا کا مطلب کہ ذات۔ حق تعالیٰ اتنا غلبہ ہو جاوے کہ انسان کے اندر میں حق تعالیٰ کی شعور کے دوسری کوئی بات نہ رکھے اور فنا درفنا کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی فنائی کی بھی خبر نہ ملے یہ سارا خیال لوایح کی مندرجہ ذیل ریاعی میں موجود ہے
آنر کہ فنا شیوہ و فقر آینست
نی کشف و یقین نہ معرفت نہ ددینست
رفت اوز میان حمین خدا ماند خدا
"الفقر اذاتم ھواللہ" اینست
ترجمہ: جنہوں نے فنا کو اپنا شیوا اور فقر کو اپنا طریقہ بنایا اُن کے لیئے نہ کشف تہ یقین نہ معرفت اور نہ دین جس کہ سبب کچھ چلا کیا گیا اور فقط جدا ہی خدا رہا فقر کا اختتام خود خدا ہی کا یہ ہی مطلب ہے کہ بیان العارفین میں صفحہ نمبر 102 پر بھی خیال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اُم ویسی سے مراد ہے کہ نہ قتف نہ کہ اُمت نہ یقین نہ معرفت یعنی فنا اور فقط اِس لحاظ بیان العارفین فقر یا فقیری کو بھی ذاتے خود مقصد بتایا گیا ہے نبی کریم ﷺ کا قول الفقر فخری کا بھی مطلب بنایا ہے
تشریح : شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ کے حوالے سے صفحہ نمبر 22 پر ملتی ہے جو انہوں نے تما ورجات کشف ، کرامات غوثیہ اور شغی کو قبول نہ کیا لیکن آخر میں فقیری کا درجہ قبول کیا ہے۔ خدا کائنات اور انسان کے باھمی تعلق کی تشریح کے لیئے بیان العارفین کے صفحہ 142 پر مندرجہ ذیل اشعار موجود ہیں:
عالمی چیست بر زخی جامع
صورت خلق حق درو واقع
عالمی نیست ولی ھست نما
حق ھست ولی نیست نما۔
ترجمہ: یہ عالم کیا ہے ایک مثبتہ کہ بررخ جسم میں مخلوق اور خالق دونوں کی صورت موجود ہے عالم ہے یہ نہین لیکن لکتا ہے حق موجود ہے لیکن دیکھنے میں نہیں آتا یہان یہ بات قابلے توجہ ہے کہ مندرجہ بالا اشعار مولان جامی کے مشھور مثنوی {سلسلۃ الذھب} میں سے لئے گئے ہیں جہاں عالمی کی بجائے لفظ "آدمی" ہے اصل میں اور عبارت اِس طرح ہے
آدمی چیست برزخی جامع
صورت خلق و حق درو واقع
ترجمہ: انسان کیا ہے؟ وہ ایک برزح کا مجموعہ ہے جہاں مخلوق اور کی صور ت میں موجود ہے اِس طرح جہان تک پہنچنے دو سطور کا تعلق ہے یعنی
عالمی نیست ولی ھست نما
حق ھست ولی نیست نما
کہ یہ دو سطور بنیادی طور پر مثنوی مولانا رومی کے پانچویں دفتر کے مندرجہ ذیل عنوان سے لے کر تخلیق کی گئی ہے
مثال: عالم ھستِ نیست نما و عالم نیست نما
ترجمہ: موجودہ عالم جو بظاھر معصوم ہے اور مخدوم عالم جو بظاھر موجود ہے رومی نے مذکورہ موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے۔
نیست را بنمود ھست آن محتشم
ھست رابنمود بر شکل عدم۔
یعنی اُس جا ہو جلا نے نیست کو ھست ظاحر کیا ہے اور موجود گو معدوم کی شکل میں دکھایا ہے دراصل یہ مولانا رومی کا نھایت پسندیدہ موضوع ہے، ایک دوسرے جگر پر وہ اِس طرھ ایک ہے اور واضح کرتے ہیں
این جھان نیست چون ھستان شدہ
وآن جھانِ ھست بس پنھان شدہ
یعنی یہ عالم جو نیست ہے وہ ھستی والا لگتا ہے جبکہ وہ عالم جو اصل میں ھستی والا ہے وہ مخفی ہے لیکن دوسری جگہ پر وہ فرماتے ہیں
ماعدم ھائیم وھستی ھانما
تو وجود مطلقی ھستی ما
ترجمہ: ھم عدم یعنی کچھ نہین پر ظاھر میں ھستی یا وجود کے ساتھ ہیں اور توں وجود متعلق ہے اور ہمارا وجود میرے ساتھ ہے اسلامی تصوف عام طور پر اور سندہ کے تصوف عام طور پر اور سندہ کے تصوف عام طور پر اپنے پ کہ پہچانا اور وجود کی نفی کے پہلو انتہائی واضح ہیں اِس سلسلہ میں شاہ کریم نے یہ شعر خاص طور پر قابلے ذکر ہے
پھرین پا ڻ وڃاءِ پا ڻ وڃائي هوءَ لهه
توهان ڌار نو سپرين ، منهن منجهين پاءِ
اِس خیال پر اِتنا زور لیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ طالب چاہیئے کہ وہ اپنا وجود کہ دے اِس طرح کرنے۔ اُن کو وہ راز معلوم ہوجائے گا جو "فصوص" اور "لمعات" میں بھی انہیں نہیں ملے گا اِس سلسلے میں یہ شعر مُلا حظہ کیجیئے
رو نفی وجود کہ درخود یابی
سری کہ نیابی ز " فصوص" و "لمعات"
یہ دو سطور در اصل جامی کے اِس رُباعی میں کسے لی گئی ہیں جو استعۃ المعات کے آخر میں ذکر کی گئی ہیں۔
توحید حق ای خلاصہ مخترعات
باشد بح سخن یافتن از ممتعنات
رو نفی وجود کہ درخود یابی
سری کہ نیابی ز " فصوص" و "لمعات"
ترجمہ: حق تعالیٰ کی توحید کے متعلق تمام نئیں کاوشوں کا وہ خلاصہ ہے کہ اُن کا بیان کرنا ناممکن ہے بس جاؤ اور اپنے وجود کی تھی کردو تو تمہیں اپنے من میں وہ راحق معلوم ہوجائے گا جو فقوص اور لمحات میں بھی تمہیں نہیں ملے گا۔
جامی کے مذکورہ ریاعی میں جب دو کتابوں یعنی اِس عربی کے {قصوالحکم} اور عراقی کے {المعات } کا ذکر ایا ہے کہ اِن پر کچھ روشنی ڈالی جائے پر اِس کبھی ضروری ہے ہے کہ بیان العارفین میں اِن دونوں کتابوں کے واضح کیا جاسکتا ہے فصوص الحکم:
اسلامی دنیا کے عظیم صوفی ذھن معین الدین ابن العربی 560/ 1165/437/ 1240 کی فکر کا وشوں کا نتیجہ ہے فقہ لفظ کی لغوی معنہٰ نگینہ کی ہے اور اصطلاحی معنیٰ راض کی ہے پوری کتاب کل 27 فصوص پر مشتمل ہے اور فص میں حضرت آدام سے لیکر خاتم النبیا تک ھر نبی کے حوالے سے اُن کی مخصوص حکمت الاھی کے اسراروں کی تشریح اور توضیع ملتی ہے مسئلن پہلی فصص مشھور حدیث قدوسی {ان اللہ خاق آدم اعلیٰ صور تھی} یعنی بیشکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اُس کی تفھیم دی ہے اُس باب میں یہ بحث کی غی ہے کہ انسان کس طرح خدا کی ذات مظھر ہے اُس کے بعد اُسی فصل میں دوسری مشھور قدسی حدیث میں {کنت کنزاً مخفیاً فاحبیت ان اُعرف فخلقت الخلق}یعنی میں ایک چھپا ہوا تھا پھر میں نے محبت الفن کی وجہ سے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں اُس لیئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا ایس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اِبن عربی فرماتے ہیں کہ دراصل یہ وہی ذات ہے جو حقیقتً کے لحاظ سے حاک ہے کہ ظاھر کے لحاظ سے خلق یا مخلوق ہے دوسرے الفاظ میں ذات حق کا ظاھری پہیلو یہ عالم ہے اور عالم کا باتنی پہلو حق تعالیٰ کی ذات ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بخوبی عربی خبردار کرتے ہیں کہ اُس کا کوئی اور مطلب نہ سمجھنا چاھیئے کیونکہ حق پھر بھی حق ہوتا ہے اور مخلوق مخلوق ۔ اِس حقیقت وہ صحیح بخاری کی اِس حدیث سے واضح کرتے ہیں کہ قان اللہ ولم یکن معحو ۔۔۔۔۔ یعنی اللہ تعالیٰ تھے اور اُن کے ساتھ دوسری کوئی چیز نہ تھی یا جس طرح اُس کی وضاحت میں صوفیوں کا قول ہے {الآ کما کان} وہ اِس طرح ہیں جس طرح تھے۔
اِبن عربی زندگی کے آخری سال بغداد میں گذارے اور وہی انتقال کر گئے بغداد میں وہ شیخ شھاب الدین سھروردی سے ملے اور اِس کے علاوہ صدر الدین کو نوی سے بھی اُن کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ آرزہ سے بہت متاثر ہوئے ابن العربی وحدت الوجود کے منفرد عقلی تشریح کے اسلامی تصوف پر نھایت دیرپا اثرات چھوڑ ے ہیں اور اُس لیئے انہیں شیخ اکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے
بیان العارفین میں ابن عربی کے تظریہ کے حوالے سے تنزیحہ اور تشبیحہ کی بحث
بیان العارفین میں اِبن عرب ی کا جس مخصوص نقطہ نظر سے حوالہ ملتا ہے، " خدا اپنی ذات کی وجہ سے احد ہے اور صفات کی وجہ واحد" اِبن عربی یہ بحث خصوس الخلم" میں کئی مقامات پر کیا ہے خاص طور پر فصے اسماعیلی اور یوسیفی میں اِس طرح کے الفاظ لیئے ہیں ابن عربی کا مشھور شاوح کاشانی اِس عَمر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں " حق تعالیٰ ذات کی وجہ سے امر ہیں۔ اور وہاں کسی قسم کی بھی کثرت نہیں ہے لیکین علومیت کے لحاظ اُن کی بیشمار نسبتیں ہیں اُن کی مثال ایک (۱) کے عدد کی طرح ہے جس کی نسبتاً دوسرے تمام اعداد سے نسبت ہے
اسی طرح قص شعیبی میں فرماتے ہیں کہ عالم میں جو کثرت نظر آتی ہے وہ سب اُس واحدِے حقیقی میں موجود ہے جو وجود متعلق ہے اور کثرت کی صورت میں ظاھر ہوا ہے۔ بیان العارفین ایک اور بحث تنزیہ اور تشبیھہ کا ہے جہان پھر وہی پھر وہیں فصوص العلم والا نظریہ دورایہ کیا ہے بنیادی سوال یہ کہ خدا کی ذات منظرح ہے یا مشتبحہ دونوں ! اِبن عرب اِس کی نہایت زور و شور تائید کرتے ہیں کہ خدا کی ذات منزہ بھی ہے اور شبہ بھی وہ اِس بات پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مخفن تشبیحہ کا مطلب خدائی ذات کو محدود کرنا ہے اور محض تشریح کا مطلب خدائی ذات کو معید کرنا ہے اِس سلسلے میں اُس کے مندرجہ ذیل اشعار ملاحضہ ہو
{فان قلت بالتنزیہ کنت مقیداً – وان قلت بالتشبیہ کنت محدداً}
ابن عربی یہ تمام بحث فص نوحی میں نھایت وضاحت سے کیا وہ اِس خیال کہ ہیں کہ حضرت نوح ؑ کی دعوت محض تنزہ پر مبنی تھی جب کہ اُن کی قوم محز تشبحہ کا عقیدہ رکھنے والی تھی اگر حضرت نوح ؑ کی دعوت میں تشریح اور تشبیحہ دونوں ہوتے جس طرح رسولﷺ نے کیا تہ ضرور کامیا ہوتے۔ اِبن عربی کے مطابق ہیں ہم متکھی شیً کے اندر تنزیحہ اور تشبیحہ دونوں موجود ہیں۔
بھرالحال اِبن عربی کے حوالے سب سے زیادہ اھم عبارت جو اُن کے مخصوص نظریہ وحدت الوجود کی بنیاد ہے اور جو بیان العارفین میں ملتی ہے{فسبحان من اظھر الاشیأ وھو عینھا} لیکن یہ عبارت فصوص الحکم میں نہیں بلکہ فتوحات مکیہ کی دوسری جُلد میں ملتی ہے جو فخیم کتاب ہے، جو انہوں نے "انتقار" سے فقط دو سال پہلے مکمل کی تھی اور اُس کتاب کی تصنیف پر انہوں نے تقریباً 35 سال صرف کیے تھے اِسی عبارت ان کے مندرجہ ذیل اشعار مُلاحضہ ہوں،
فما نظرت عینی الیٰ غیر وجھہ
وما سمعتہ اذنی خلاف کلامہ
فکل وجود کان فیہ وجودہ
و کل شخص لم یزل فی منامہ
ترجمہ: میری آنکہ نے اپ چھرے کے سوائے اور کچھ نہ دیکھا میرے کانوں نے اُس کی آواز کے علاوہ اور کچھ نے سنا اور ھر چیز کے وجود میں اُ کا وجود ہے اور ھر شخص ھمیشہ سے اُن کی خلاوت گاھ میں ہے اُسی نقطہ نظر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محققین کے پاس خدا کے وجود کے علاوہ دوسری کوئی چیز موجود نہیں ہے جہاں تک موجود ہونے کا تعلق ہے لیکن ہمارا وجود بھی اُن کے وجود سے ہے اور جو وجوسد غیر کے سبب سے ہے وہ عدم کے بررابر ہے اُس لیئے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا عارف حق کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں دیکھتا اِس سلسلہ میں اِبن عربی کا مشحور عربی شعر ملاحضہ ہو:
وفی کل شی لہ آیۃ
تدل علی انہ واحد
ترجمہ: ھر چیز میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ واحد ہے اِس میں وہ اِس طرح ترمیم کرتے ہیں
وفی کل شی لہ آیۃ
تدل علیٰ انہ عینۃ
ترجمہ: ھرچیز میں ایک نشانی ہے جو دلیل دیتی ہے کہ وہ ھر شی کا عین ہے اِسی طرح خدا اور عالم یا خالق اور مخلوق کے باھی نسبت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجودے حقیقی واحد سے اور جو کچھ نظر آتا ہے یہ حواسوں کے ذریعے محسوس ہوتا ہے یہ دونوں عین واحد کے پہلہ ہیں اگر وحدت پر نگاھ ڈالی جائے گی تو حق ہے لیکن کثرت والی نگاھ ڈالی جائے گی تو وہ مخلوق ہے اور اُس سے خلق کے نام دینا چاھیئے اِس نظریہ کی ایک فارسی شعر نھایت آسان وضاحت ملتی ہے
صفات و ذات چو ازھم جدا نمی بینم
بھرچہ می بینم بجز خدا نمی بینم
ترجمہ: صفات اور ذات جب میں ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھنا اُس سے جو کچھ دیکھتا ہوں خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا۔
سندہ و ھند میں اِبن عربی کے نظریات کا اثر:
سندہ ھند میں اِبن عربی کے نظریات کیے اور کب پہنچے اِس سلسلہ میں گلزارے ابرار کتاب میں سے کافی معلومات ملتی ہے کتاب کے مؤلف غوثی موجب آٹھویں، نویں، دسویں صدی ھجری کے صوفیوں کے بڑے مراکز تھے، خاص طور پر گجرات چشتی سلسلہ کا بڑا مرکزہ تھا جو بختیار کاکی کے زمانے میں قائم ہوا،
چشتی سلسلہ کے بزرگان بنیادی طور پر وحدت الوجود کی طرف مائل تھے
اور وہ سب سے پہلے اِبن عربی کی تحریروں ہے مانوس ہوئے دسویں صدی ھجری یا 16 ویں صدی عیسوی میں سندہ کے صوفیائے کرام کی وہاں آمدو رفت نے علمی اور فکری تعلیمات کو مزید مستحکم کیا، گجرات ٹھٹہ کے دوراں جنداللہ پاٹائی 962ھ 1554ء 1031 ھ 1621ء جس نے برھانپور سکونت اختیار کی اور شاہ کریم کے وہ ھمعصر تھے انہوں نے اپنی تفسیر " انوالسرار" لکھنے وقت فصوص الحکم اور اِبن عربی دیکھ تحریروں کو سامنے رکھا ہے گلزارے ابرار کے مطابق جامی کے نفجات الاسع " لوائع" اور دیگر تصنیفات۔ بر صغیر کے اندر کافی مشھور تھین جس پر بیان کی گئی علمانے تشریحیں لکھیں، بیان العارفین میں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ کریم احمد آباد گئے تھے اور ہوں صوفیا کی سماع کی محفلوں میں شریک ہوئے لحاظہ یہ ہوں کا علمی اور صوفیانہ ماحول تھا، جہاں سے اِبن عربی کے اَثرات اُ تک پہنچے یا اثر انداز ہوئے ہیں جسے مزید عالما نہ انداز میں بیان العافین کے مرُتب محمد رضا نے پیش کیا
وحدت الجود کی نظر یئے کو بڑا صفیہ میں عام کرناے پر فخر الدین عراقی اور جامی کے اثرات
دوسری کتاب " لمعات" فخر الدین عراقی تصنیف 681تا 1289 وہ اصل میں ھمدان کے تھے جو قلندروں کے ٹولے سے سیر و سفر کرتے ہوئے ملتان پہنچے وہاں اُنہیں شیخ بھاؤالدین کی صحت حاصل ہوئی جس انہیں اپنا فلسفہ اور داماد بنایا ۔ شیخ کی وفات وہ بغداد چلے گئے اور وہاں سے قوتیاں گئے جہاں شیخ صدر الدین کی صحبت رھئے جن سے حصوص الحکم پڑھتے فصوص سے متاثر ہو کہ اپنا رسالہ لمعات لکھی جس میں کل 26 لمعات اور اُس میں خدا کائنات اور انسان کے تعلق کی تشریح عشق کے حوالے سے کی مولانا جامی وفات 898 ھ لمعات سے اِتنا متاثر ہوئے جو نہ فقط اُن تشریح اشعۃ اللعمات کے عنوان سے لکھی بلکہ اُسی طرز پر اپنی اثر کتاب لوایح کے نام سے لکھی جس کے حوالے ہم پہلے دے کر آئیں ہیں۔
برِصغیر وحدتےوجوری یا حم اوست کی فکر کو عام کرنے کا سحرا بڑی حد تک جامی لوایح اور اسطتہ اللعمات کے علاوہ اُن کی شاعری پر بھی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اُن تصویرات کو مزید عام فھہ اور قابلے قبول بنادیا یہ جامی کے شاعری کا کمال تھا جس نے انہیں مقبولیت بخشی جامی کے فکر اور عرفان کا بر صغیر میں پہنچنے کا دوسرا میں یہ تھا کہ وہ اتفاقن کے موجود علائقے حرات کے تھے، اُس لیئے حرات کا ھندوستان کے قریب ہونے کے سبب آمدورفت اور راستے کا زیادہ امکان تھا۔ سیر العارفین کے مصنف جمالی دھلوی حرات میں جامی کے مھمان بنے تھے اُسی طرح سندہ کے کچھ عالم بھی براہِ رات جامی سے مستفید ہوئے تھے گلزار ابرار مولانا قاسم کا حر کا نام لیا ہے میر علی شیر معیارے سالکان طریقے میں بھی ایسا ذکر کای ہے عراقی کے لمعات اور بیان العارفین میں فکری لحاظ سے کچھ باتیں مشترکہ ہیں سب سے پہلے یہ شعر جو صفحہ نمبر 143 پر موجود ہے۔
آن پادشاہ اعظم دربستہ بود محکم
پوشید دلق آدم، ناگاہ بر در آمد
ترجمہ:ۃ وہ عظیم جو ایک قلعے محفوظ بیٹھے تھے اچانک آدم کی پوشاک پہٹ کر ظاحر ہوئے ہیں یہ بیت لمع 24 میں دیا گیا ہے ان سے پہلے خواجہ بداللہ انصاری کا عہ قول بھی موجود ہے
"حق تعالیٰ خواست کہ صنع خود راظاھر کند، عالم آفرید،خواست کہ خوردرا ظاھر کند،آدم را آفرید"
یعنی جب حق تعالیٰ نے چاہاکہ اپنی تخلیق کو ظاھر کریں تو عالم یا جہان کو بنایا لیکن جب انہں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاھر کرے تو آدم کو پیدا کیا لمعات اور بیان العارفین میں مزید مشترکات اور اقوال کی شریح آخر میں حوالوں کی صورت میں دی گئی ہے
ابن عربی کے خصوس الحکم کو فتوحاتے مکیہ فخرالدین عراقی کی لمعات اور جامی کی لوایح کے علاوہ جس دوسری کتاب کے اشعار اور اِشات بیان العارفین میں ملتے ہیں وہ شیخ محمود شبستری 650ھجری 1253ء کی گلشن راز ہے جو انہوں نے 417 ح 1317ء جس میں انہوں نے 15 سوالات کا تفصیلع جواب دے کر تصوف کے بنیادی مسائل خدا، کائنات انسان کے تعلق کی وضاحت کی ہے بیان لاعارفین صفحہ نمبر 144 پر یہ شعر ملتا ہے:
روا باشندانا اللہ از در ختی
چرا نبود روا از نیک بختی
ترجمہ: اگر درخت کے لیئے اِن اللہ ، میں جُدا ہوں کہنا جائز ہے تو پھر کسی نیک بخت انسان کے لیئے یہ جائز ہے کیوں نہیں ہے؟ در اصل یہ شعر گلشن راز کے ساتویں سوال کے جواب میں کے جواب میں موجود ہے اِسی طرح یہ شعر تھوڑی تبدیلی کے ساتھ صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے جو اس طرح ہے
کسی مرد تما مست کز تمامی
کند با خواجگی کار غلام
ترجمہ: تمام کامل بزرگوں میں وہ زیادہ کامل ہیں جو درجہ اول پر پہنچنے کے بعد بھی بندگی کے راستے پر گامزن ہے گوکہ مثنوی مولانا رومی 1204ھ 1273ھ کا بیان العارفین میں براہِ راست کوئی حوالہ یا نہیں ملتا تاھم شاہ کریم کے کئی ابیات اور کچھ اقوال میں ترمیم براہِ راست رومی کے خیالات کی ترجمانی ملتی ہے بیان العارفین میں ایک جگہ ایکو کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عام لوگ ایکو کی آواز سے متاےر ہوجاتے ہیں لیکن ایکو میں پھونکنے والے کی طرف توجھ نہیں جاتی۔ مولانا رومی نے مثنوی کا آغاز اِیکو اس تمثیل سے کی گئی ہے کہ ایک طرف سبب اُس لیئے آواز نکاکسی ہے کیونکہ اُس اپنے اصل درخت سے کاٹ کر ایک کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ ایکو اصل اندرونی ہے جو اپنے اصل سے ملنے کے لیئے بیتاب ہے،
صوفیوں کا نظریہ ہے کہ وہ ظاھری حواسوں سے خدا کی ذات کو محسوس نہیں کرسکتے، اُس کے لیئے مخصوص حواسوں کی ضرورت ہے، رومی نے اسی خیال کو نھایت شد اور مد سے کئی مقامات پر بار بار بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں:
گوش خر بفروش و دیگر خوش خر
کین سخن رادر نیا بد گوش خر
ترجمہ: یہ گدھے والے کان بیچ کہ دوسرے خرید کرو کیونکہ اِن گدھے والے کانوں سے تم وہ خاص آواز نہیں سن سکو گے،شاہ کریم نے اپنے اِس شعر رومی کا وہ ہی مفہوم بیان کا ہے۔
هي ڪن گڏهڻا وڪڻين ، ڪن ڪي ٻيا ڳنهيج
تنين سان سڻيج، پريان سندي ڳالهڙي
صوفیوں کے پاس صورت اور معنیٰ کا فھم بنیادی حیثیت رکھتا ہے مثنوی رومی میں صورت اور معنیٰ کا فھم بنیادی حیثیت رکھتا ہے مثنوی رومی مین صورت اور معںیٰ پر مختلف مقامات بڑی بحث کی گئی ہے صورت سے مُراد یہ ظاھری دنیا ہے جس میں انسان یہی شامل ہیں اور معنیٰ سے مراد مخفی دنیا ہے جس ذات خدا وندی بھی شامل ہے شاہ کریم نے اُسی خیال کو انتھائی خوبصورت انداز میں سندہ کی ایک مشحور لوک داستان ماروی کے حوالے سے اِس طرح بیان کیا ہے
صورت ليکي مارئين، معني ليکي مارئين
عمر مون جي چت ، اوطاقون ٿرن ۾
شاہ کریم کے اِس بیت کو ، رومی کے مندرجہ ذیل اشعار سے ممنت کی جاسکتی ہے
صورتش بر خاک وجان بر آسمان
لامکانی فوق وھم سالکان
ترجمہ: بدن کے لحاظ سے وہ زمیں پر ہے لیکن ر وح کے لحاظ سے وہ لامکان پر ہے یہ لامکان سالکانے کے وہم اور گمان سے بلا ہے اِس سلسلے رومی کا ایک دوسر مشھور شعر ملا حضہ ہو،
گر بظاھر عالم آصغر توئی
دان بمعنی عالم اکبر تو ئی
ترجمہ: گو کہ بظاحر توں "عالم اصغر " ہے لیکن اصل میں "عالم اکبر" بھی توں ہی ہے ،
شاہ کریم نے ایک شعر کے اندر قران پاک کی آیت " مکرو و مکر اللہ واللہ خیرالماکرین" کی تصنیف کی ہے اُس کا مطلب ہے کہ محبوب سے میلاپ بھتر ہے یا جدائی ، یہ ذات خداوندی پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہی تدبیر کرنے والے ہیں :
سوئي صلح سڄڻين، سوئي ڦوڙائون
والله خير الماکرين، ايهي ميڙائون
مولانا رومی نے بھی اُسی طرح کی تصنیف کی ہے اور وہی خیال اِس طرح پیش کیا ہے
مکر حق سر چشمہ این مکر ھاست
" قلب بین اصبعین" کبریاست
ترجمہ: ذاتِ حق کی تدبیر تمام تدبیروں کا سرچشمہ ہے کیونکہ مؤمن کا قلب ذات کبریا کے دو اُنگلیوں کے درمیان میں ہے، تمام صوفی مشھور حدیث قدوسی کا حوالہ دیتے ہیں "______" یعنیٰ میں مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاھ کے میں پہنچانا جاؤں جس کی وجھ سے میں نے مخلوق کو پیدا کیا ۔ مولان رومی نے اِبنے مثنوی میں اِس حدیث کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی ہے جس میں ظاھر ہے کہ محبت کا پہلو زیادہ غالب ہے، رومی فرماتے ہیں
جملہ معشوقست و عاشق پردہ ای
زندہ معشوقست و عاشق مردہ ای۔
ترجمہ: سب کچھ وہ معشوق ہے اور عاشق پڑدے میں محفوظ ہے معشوق ہی زندہ ہے اور عاشق تو مردہ ہے۔
بیان العارفین کے صاحب نے اوپر اُسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دو ادبیات لکھے ہیں :
پاڻهي سلطان پاڻهي ڏي سنيهڙا
پاڻ ڪر پاڻ لهي، پاڻ سڃاڻي پان
دوسرا اشعار:
اسين سڪون جنهن کي، سي تان اسين پان
هاڻي وڃ گمان، صحيح سڃاتا سپرين
اگر غور دیکھا جائے تو اِن دونوں ابیات میں اُسی حدیث شریف کا کا اور رومی کا مرکزی خیال کار فارمان ہے کہ اصل وہ خودہی سب کچھ اور انۃیں پہنچانے کے لیئے یہ سب کچھ ہیں،
اِس طرح نفی، اثبات یا لا اور الا کے متعلق رومی اور شاہ کریم کے خیالا میں کافی حد تک معماصلت و مشابہت ملتی ہے مثال کے طور پر رومی کا ایک شعر :
زانکہ در الاست اواز لاگشت
ھر کہ درالاست او فانی نگشت
ترجمہ: لا (کچھ نہیں) ہوگئے ہو لیکن الا کی طرف اگے بڑہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ توں غلام بھی ہے اور آقا؟ اُن کا ایک دوسرا شعر ہے:
لا ۾ لوڌي ڪڍ الا م لاهه لک سين
جو مظهر سندو ماڙوئين، تنهن ڪيئن ڪرين وڍ
ترجمہ: جو ایلا کی منزل پر پہنچا جو وہ لا میں سے گذر گیا اور جو اِلا پر پہنچا وہ فنا سے بچ گیا اور اب اِس کے مطابقت میں شاہ کریم یہ شعر ملاحض فرمائی جو انہوں نے قاضی قادن کے اِس بیت کے جواب میں کہا تھا۔
اِس بیت سے ظاحر ہے کہ شاہ کریم نے فقط نفعی اور اِلا یعنی شبات کو واضح کیا ہے بلکہ اُس کے ساتھ انہوں نے اِس طرف بھی اِشارہ کیا ہے کہ اِنسان جو ذات خداوندی کا مظحر ہے اُس کو نظر انداز کیسے کیا ج سکتا ہے
عرفان شاہ کریم
خدا انسان اور کائنات کے باھمی تعلق کا شعور صوفیائے کرام کا بنیادی مھور ہوتا ہے اور تمام تصوف کا نظریہ اپسی نسبت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہے عام طور پر صوفیوں کے پاس بہ نظریئہ زیادہ مقبول ہے کہ یہ دنیا ایک ٰایکو یعنی اصلیت سے خالی ہے اصل حقیقت صرف ذات خداوندی ہے لیکن انسان کو اِس کائنات میں ایک خصوصی حیثیت شامل ہے ، اُسی نظریہ کو دوسرے الفاظ میں اِس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی اپنی صفات کو ظاحر کرنے کے لیئے یہ جہان پیدا کیا لیکن اپنی ذات ظاھر کرنے کے لئے آدم کو بنایا اِسی لحاظ سے انسان خدا کی ذات آئینہ ہے ، خلقی آدم علیٰ صورتھی کا بھی یہی مطلب ہے
انسان اور خدا کے تعلق کو واضح کرنے کی خاطر صوفیائے کرام نے زیادہ تمثیلات کا سہارا کیا ہے کیونکہ یہ حقیقت سمجھانے میں بہت مشکل ہے۔ سادے میں سادہ ایکو اواز اُنکے ٰایکو کی ہے دوسری مثال پانی اور اس سے پیدا ہونے والے بُلبلے یا پانی اور اُس میں ہونے والی لھروں کی ہے مولانا رومی نے اپنی " جوت طبع" سے کٹے ہوئے درخت کی لکڑی بنی اور اُن کو ملنے والے تمثیل سے واضح کیا ہے ۔
بھرالحال انسان اور خدا کے تعلق کی یہ وضاحت ایک لحاظ سے آسان بھی اور دوسرے لحاظ سے مشکل بھی ہے، تمثیلی انواز کو چھوڑ کر جب اس کی تشریح خالص عملی اور فلسفیانہ لحاظ سے کی جائے تو نھایت گھمبیر اور دقیق ہو جاتی ہے محی الدین اِبن عربی جسے عالمے اسلام کا اِس لحاظ سے سب سے بڑا صوفیوں میں شمار کیا جا تا ہے انہوں نے اپنی تصنیفات میں خاص طور پر فصوص الحکم میں اِس طرح کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے اُس کے مقابلے میں مولان رومی نے اپنی مثنوی میں بیادی طور پر تمثلی انداز اِختیار کر کے اُس کی عقلی تشریح بیان کی ہے
صوفیائے کرام کی نظر میں جس انسان کو یہ سمجھ اور شعور حاصل ہو جا تا ہے وہ عارف ہے اور اُسی طریقے کو معرفت کہتتے ہیں صوفیائے کرام کی نظر میں عالم فقط اشیاءَ کے ظاھری پہلو تک محدوسد ہوتا ہے جبکہ عارف کا تعلق براِ راست حقیقت وے ہوتا ہے اور اُس رابطے کا بنیاد اُن کا ذاتی مشاھدہ تجربہ ہوتا ہے تاھم وہ مشاھدہ مخصوص تربیت اور ریاظت کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا اور اُس لیئے مرشد یا شیخ کی ضرورت ہوتی ہے
بیان العارفین سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ کریم بنیادی طور پر فکر زھد کے صاحب تھے تاھم وہ عرفان عالیہ کے صاحب بھی تھے ایل طرف اُن کا عرفانہ بیان العارفین میں شامل اُن ملفوظات سے عبان ہیں، دوسری طرف اُن کی شاعری پڑھنے سے اِس بات پتہ چلتا ہے کہ وہ زاحد اور عارف تھے ۔ ایک طرف اُن کی ملفوظات چادر اوڑنے سے لیکر پگڑی پہننے سے لیکر پاؤں میں جوتا پہننے اور نہ پہننے کے تمام تفصیلات بیان العارفین میں ملتے ہیں لیکن اُسی وقت آپ کے ایسے اقوال بھی ملتے ہیں جو اُن کے وسیع المشرب عارف کی حیثیت کو ظاھر کرتے ہیں مثال کے طور پر فقیروں کا ھجرہ یہ زمین اور اسمان اُن کی چھت ہے کرامت کے لیئے اُن کا کہنا ہے کہ کرامات خرایات ہیں
اور شراب کی طرح حرام بلکہ صاف صاف کفر ہے، اسی طرح کا اشتِقاق کرتے ہوئے فرمایا کرنے سے مراد دائمی فکر اور "ق" قُربِ الاھی اور "ی " سے مراد خدا سے یاری اور " ر " سے مراد ریاخت ہے
پیر کسےکہتے ہیں ؟پیر میں کونسے اوصاف ہونے چاہیئے؟اس کے جواب میں فرمایا کہ جس شخص نے مرتبے کی لالچ نہ رکھی وہ پیر ہے اور میں فقیروں کو پیر سمجھتا ہوں کیونکہ پیر ان کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آجائےفرمایا کے پیروں کو سب کام کرنے چاھیئے سمئلن زمین کو آباد کرنا خلقے خدا سے تعلق رکھنا یہ بھی کہا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ پیر ھی دیتا ہے وہ بلکل غلط ہے جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے اور اُن سے ھی سمجھنا چاھیئے ایک دفعہ ایک شخص کہ وہ اپنے آپ سید کہلا رہئے تھے اُ کو بُلا کر کہا کہ توں اپنے آپ کو فیر کیوں ںہیں کہلاتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیغمبر ؑ نے خود فرمایا کہ طلاب خدا کو چاھیئے کہ کسی طلب لالچ یا مراد کشف اور کرامات قرب اور معرفت کے لالچ سے خدا کو یاد نہ کرے بلکہ بغیر کسی مطلب کہ اُنہیں یاد کیا جائے کیونکہ یہ خود خدائے ذوالجلا کی خواھش ہے کہ اُنہیں بغیر کسی مطلب کے یاد کیا جائے بیان العارفین میں ایسے کئی اقوال و ملفوظات ملتے ہیں جو شاہ کریم کے عرفان کو اسلامی تصوف کی تاریخ مین ایک ممتاز منفر اور مقام دیتے ہیں۔
اِس سلسلہ میں اُن کی شاعری پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہواں شاہ کریم اپنے عرفان کے ذریعے بلکل نئیں روشنی ڈالتے ہیں مثلنً آپ قاضی قادن کے ابیات کو پسن فرماے تھے اور اکثر مریدوں کے سامن ے وہ پڑھتے تھے، ھرچند کے قاضی قادن اپنے دور کے جید عالم اور فاضل تھے، تاھم اُن کے مندرجہ ذیل اشعار اُ کی مشامداتی کیفیت کے آئیندار ہیں
سائر ڏيئي لت، اوچي نيچي ٻوڙئي،
هيڪائين هيڪ ٿئو ، ويئي سڀ جهت
شاہ کریم کا مشاھدہ ذرا مختلف ہے اور انہوں نے اپنا نظریہ اِس طرح پیش کیا ہے
سائر ڏيئي لت، اوچي نيچي ٻوڙئي
نابودي نه ٿئي ، ايءَ ناديدي جهت
قاضی قادن کا ایک دوسرا متعد ہے
لا ۾ لاهيندي ڪن کي، لا مورهين ناهه
بالله ري پريان، ڪٿ نه ڏسجي ڪي ٻيو
شاہ کریم نے اُن کے جواب میں سے پڑاح جس میں نفی اور اتسبات کے ساتھ انسان جو خدائی مظھر ہے اُس کی حیثیت کو نھایت خوب کے ساتھ واضح کیا ہے،
لا ۾ لوڌي ڪڍ الا م لاهه لک سين
جو مظهر سندو ماڙوئين، تنهن ڪيئن ڪرين وڍ
سالک صوفیوں کی نظر میں نفی اور اثبات یعنی لا اور الا کے علاوہ سلوک کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور شاہ کریم کے ابیات میں یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے
ھر چند کے شاہ کریم صوفیائے کرام کہ اُس نظریہ ہے اصولی طور پر متفق ہیں کہ انسان کا وجود محبت کا مرحونہ منت سے اور انسان کو اپنی اصلی محبوب سے ھر وقت ھر وقت رابطے میں رھنا ہے اور اُن کے خوشنودی کے لیئے جس میں اپن کی اپنی خوشنودی بھی شامل ہے کوشش کرتی ہے لیکن محبت کے تقاضے کی سبب وہ تعلق نھایت نازک وعیب ہے خاص طور پر جب وہ حاصل ہوجاتا ہے تو اُن کی عقلی تشریح نہیں کی جاسکتی
ڪا جا پر پرين ، نه سا سئي نه ٻڌي
متيون سڀ منجهن انهيءَ ڌٺي قضي
شاہ کریم اپنے مشاھدے کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ سلوک یا محبت کا راستہ اِتنا آسان بھی نہیں جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا اُن کو گمان ہے کہ وہ اُ سی کی تکمیل کر چکے ہیں
آهي اهڃائو، پير پريان جو جيڏيون
جنين ساڃائو، تنين تان نه پروڙئو
دیباچہ
از مصنف محمد رضا
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
تمام تقریباً اور تنقید جو سوچ کی سحر سے دوا اور عقل کے دائرے سے باھر ہے اُس سے خالق کے ہے جس نے سالکان کی زبان کو معانویت کی راہ دیکھائی اور عارفوں کو یقینی پہچان بخشی قول مبارک ہے کہ
ترجمہ میں تیری شناس نہیں کر سکتا تیری ذات ہی تیری ثنا کی پہچان رکھتی اُس لیئے خدا کے بندے اتنی کی تن کی وادی ملی گم ہیں موھدوں کے قلوب ذات کی فکر میں حیرت زدھ اور اپنے آپ ناقص سمجحتے ہیں اپس کی راہ میں صفائی اور پاکیزگی اندھیرے سے زیادہ نہیں وہاں عارفانا حق کے دلوں کے پرندے وحدت کے وادی میں چیز دہ و سرگرداں ہیں۔
سبحان خالقی کہ صفاتش ز کبریا
بر خاک عجز می فگند عقل انبیا
گر صد ھزار قرن ھمہ خلق کائنات
فکرت کند درصفت و عزت خدا
آخر بعجز معترف آیند کای الہ
دانستہ شد {۱} کہ ھیچ نداستہ ایم ما
سبحان قادری کہ بر آئینہ وجود
بنگاشت از دو حرف دوگیتی کہ مائشاء
پاکیزگی اُس خالق کے لیئے جس کی کبیرائی کی صفات بینوں کے عقل کو بھی عاجزت کرتی ہے، ھر چند کے سینکڑوں ھزاروں برسوں سے اِس کائنات کی مخلوق خدا کی صفت اور عزت پر فکر مند ہے لیکن آکر کام اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ بیشکہ ای اللہ پاک نے ہمیں یہی کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں پاکیزگی اُس قادر کریم کی جس ہ وجود کے آئینہ پر فقط دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ چاھتے یں اُسی طرح ہی ہوتا ہے حیرت ہے، قادر کے اُ قدر پر اور سانبحہ کی اپس "سنعت رپ جس نے انسانی گروھوں کو ذاتی اور صفاتی کے لحاظ سے مختلف اور الک بنایا جسس نے فعل کے اِرادے اور عمل کے صادرنے ہونے کے سلسلے میں سالکان کی راہ کی صورت اور معنیٰ کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ اور ایک دوسرے کا ناقض بنایا جیسا کہ ارشاد خدا وندی ہے
خداوندی کہ بی شبہ است ومانند
بقدرت بر خداوند خداوند
خداوندی کہ اورا نیست ھمتا
کہ زیر ھستی اور جملہ اَشیا
یعنی پھر اُن مین سے کچھ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے اور کچھ درمیانی چال چلت والے ہیں اور کچھ لوگ نئیں میں سبقت کرنے والے ہیں
ترجمہ: خدا جو ھر شخص سے بالاتر ہے اور جس کا کوئی ثانی نہیں جو اپنی قدرت سے تمام خدائوں کا خدا ہے، وہ خدا جس کا کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں جس کے زیرِہ ھستی تمام چیزیں اور خزانہ میں صلوت اور سلام کے موتی گوحر ابدار کے لیئے اور ہمارے سردار کی بارگاھ اور اُس کے گنبذ پر نچھاور ہوں جواُس کے اِشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم جو قل حو اللہ کے نور کا چشم ہے جو لیففہ لک اللہ کا خاص محاطر ہے جو لینفروک اللہ نصر عزیز کے سرف سے مشرف ہے یعنی کے محبوب خاص حضرت محمد ﷺ جس نے رب العزت کے اُ سپسندیدہ بننے کی سوچ سمجھ سے پیروی کی اور اُن کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی نگاہ میں رکحا وہ بدت اور گھمراہی کے کڈھے سے نکل کر سلامتی اور امن کی جھولی میں مامون ہواوہ جھوٹ اور اندھعرے میں فریب نکل کہ ھدایت کے راستے پر گامزن ہوا
برقامت او {۲} قبای لولاک
زیباو مناسب است و چالاک
ترجمہ: اُن کے بدن مبارک پر لولاک کی پوشاک بہت خوبصورت اور مناسب ملتی ہے
صلی اللہ علیہ فی اللیل اذا یغشیٰ والنھار اذا تجلیِ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ المقتدا اجمعین۔
اما بعد: یہ حقیقت واضح اور روشن خیر سورج کی طرح روشن اور ۔۔۔۔ کا اثر رکھنے والے دانوروں دلیک سنج اور حق کی بات قبول کرنے والوں سے مخفی نہین ہے کہ مرید اپنے مرشد سے قول ہے اور فعل سے ایک نہیں رہ سکتے اور وہ قول و فعل تمام کے تمام کسی کو یا نہیں ہوسکتے اُس لیئے حضرت نے جو ارشادات فرمائے یا اُن کے حضور میں جو کچھ رونما ہوا اُس کو ایک دفتر میں جمع کرنا چاہیئے تاکہ مریدوں کوفیض حاصل ہو، اپسی سبب کن ہمخواہوں نے راہ حق اختیار کرنے والے احباب کے اسرار پر اُس فقیر کے ہاتھوں پہ کتاب تصنیف ہوتی اُن احباب کا کہنا تھا کہ ہمارے پیر و مرشد نے جو کچھ فرمایا اور اُس کے زمانے مین جو کچھ پربا ہوا اور سبب کچھ لکھ کر جمع کیا جائے تا کہ نامہ فلوں کے لیئے شنبح اور متکنبر ین کے لیئے تکبر توڑنے کا سامان کا سبب بنے یہ ہی سبب ہے کہ میں نے محمد رضا بن عبدالواسع عرض میر دریائی بن داروغہ گھر ساقت تھٹہ جو حضرت جی کا دلی طور پر ظاحری اور باطنی لحاظ سے خادم اور پاؤں کی خاک ہے، حضرت جی کی دل پذیر حکایات اور کرامات، سندھی ابیات، توحید اور نصیحت کے عجیب ثنا اور اعلیٰ نقات جمع کیئے ہیں، وہ حضرت سید عبدالکریم بُلڑی والے ہیں جو صاحب عزت و عرفان زاھدوں کے رہنما اور پرھیزگاروں کے پیشوا ہیں جو والایت کے عارف جو نبی کے واریث ہیں، جو سچے فنا فلاجو باقی بلا ہیں۔ جو امتے مصفطیٰ ﷺ کے چراغ اور دین کی روشندی ہیں جو اھلے تحقیق کے امام اور دوسی کے دربار مین عرف ہیں ، جو بندگان خدا کے لیئے سواری کی نشست اور ولیوں کی شمع جو اسلام کے نست اور دلیل ہیں، جو طریقۃ کا حسن اور معرفت کی کشتی ہے جو تحقیق اور کرامت کے میدان میں اُڑنے والے ہیں جو وصل کے درگاھ کےی والی اور عارفوں کا شرف وشان ہے، مریدون کے دلون کے خبر رکھنے والا اور زمانے کے کتب ہیں، خدا کے مھربانیوں کا خزانہ اور الاھی اسراروں کے دریا ہیں یعنی حضرت عبدالکریم بن سید جلا قود سلام کے کامل فرزدوں اچھے ساتھعوں سچے مریدوں اور اصل خادموں جو سب کے سب اُن کے منظوم تھے، اور انۃن کی صحبت میں اگر رہتے تھے اہن سے سن کر کے اِس کتاب کی شکل میں مرتب کیا جو ایک مقدمے و ابواب اور اختتام پر مشتمل ہے کوشش کر کے شکل فارسی الفاث سے دور رھنے کی کوشش کی ہے تاکے کسی پڑھنے والوں کو مشکل پیش نہ آئے اِس کتاب کا نام بیان العارفین و تنبہ الغافلین رکھا ہے اور رب العزت کی بارگاھ میں امید کرتا ہوں کہ اِس کتاب کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا اور پڑھنے والے سِس کتاب کے مصنف اور کاتب کو اپنی دعاوں مین یاد رکھینگے
یہ بات معلوم ہونا اہیئے کہ اِس کتاب کے اور جہان بھی ل" حضرت جی" استعمال کیا گیا ہے اُس سے مُراد ولایت کے والی اور بہت بڑی بزرگی والے اور رب پاک پسندیدہ حضرت سید عبدالکریم ہے باقی جہان تک حضرت جی کے مریدوں خادموں میں دور مخلفین کا علق ہے کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں کہ بیان کرنے سے باھر ہے اِسی لیئے ہم نے اِس سلسلے اختصار سے کام لیا ہے،
ابواب کے فہرست مندرجہ ذیل ہے مقدمجس میں پیری مریدی تاریخے پیدائش اور اُن مقامات کا ذکر ہے جہاں حجرت جی بزرگان نے رہائش اختیار کی پہلی فعل مین پیری مریدی کا ذکر اور تاریخی پیدائش کا بیان ہے۔
دوسری فصل میں اُن مقامات کا ذکر ہے جو اپنے ہمعصروں اولیا سے ملکوں کےملک دیکھنے، پہلے باب مین حق کی تلاش اور طلب، حال چھپاتا تحریروں و نفرید و رضو وظائف کے علاوہ تلقین اور نصیحتیں ہیں جو حضرت جی نے مریدوں سے ارشاد فرمائی یہ باب پھر پھر دو فصلوں پر مشتمل ہے
پہلے فعل مین نصیحتوں کے نقطے اور اُن تشریح ہے، جبکہ دوسے فعل میں وارثی وظائف بیان کیئے گئے ہیں
باب دوم مین سوال جواب ہیں جو اُن سے پوچھے گئے اور اُس نے ان کے جواب اپنے باب سوم میں صلم تواضع اور اُن کی ریاضت اور سخاوت کا بیان ہےاِس باب مین پھر دو فصل ہیں پہلی فصل میں فقط حصہ تواضح و ریاضت اور مجاھد کا ذکر ہے اور فصل دوم میں سخاوت کے بارے میں ہے باب چھارم مین سماع، صحبت، وجد اور تصوف ژکر ہے اِس باب کے بھی دو حصے ہیں پہلے حصے میں سماع اور وجد کا بیان ہے اور دوسرے فصل میں محبت اور شوق بیان ہے پانچویں باب میں اپس توحید اور اُس کے متعلق افکار اور فکر کے نقات اور اس کی تشریح دی گئی ہے باب ششم میں بیبوں ولیوں اور بزرگان کی حکایات کا ذکر ہے جو حقائق اور دکائق سے لبریز ہیں اِس باب میں بھی تین فصل ہیں پہلے فعل میں انبیا علیہ السلام کی حکایات اور آخرت کا تذکرہ بھی اِس میں اچھے شامل ہیں اور دوسرے فعل میں بزرگان سلف کی حقائق ذکر ہے تیشرے فعل میں سندھ کے ولیوں اور صوفی بزرگوں کے تصنیف نقطوں کا بیان ہے باب ھفتم میں حضرت جی کے تصرفات اور خوراک اعادت کے علاوہ اُن کے برکتوں اور کرامات کا تفصیل ہے اِس باب میں دو فصل ہیں پہلے فعل میں تصرفات کا ذکر ہے اور فعل میں کرامات و براکات کا بیان ہے :
اختتام: حضرت جی کی وجات کی تاریخ اور اپنے صاحب ذادگان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے بیان کیا گیا ہے اِس کے فصی میں دو فصل ہیں پہلی فصل میں تاریخی وفات اور دوسری فصل میں وہ گفتگو و اقوال جو اپنے بیٹون کے بارے میں انہوں نے فرما:
مقدمے میں پیری مریدی کے ذکر کے علاوہ تاریخ پیدائش کا ذکر ہے اور اۃن مقامات کا بھی بیان ہے جو وقت کے کتب سالکانے طریقت کے رھسیہ ان، سالکانے طریقت و صاحبان شریعت اور شمس الولایت کی نسبتاٌ رکھتے ہیں جو اسمان معرفت کے قطب اہلے حقیقت کے مددگارر۔ حسنے انسانیت اور اسلام کے چمک، غریبوں کے حامی اور خادم الافقرا اور پرھیزگارون پسندیدہ اور بزرگان سندھ کے افتخار، شریعت عامل اور طریقت میں کام یعنی حضرت عبدالکریم سندھی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کے متعلق ہے ،
مقد مہ :
از مصنف محمد رضا
پہلی فصل پیری مریدی اور تاریخ ولادت کے متلعق ہے دوسری فعل ان مقامت کے متعلق ہے جہان ان کے اباب و اجدادنے بودباش اختیار کی
فصل اول: پیری مریدی اور تاریخ ولادت: معلوم ہونا چاہیئے کہ سید عبدالکریم کی ولادت متعلوی یعنی مٹیاری جو سندھ کایک علائقہ ہے سال 944 ھجری میں ہوئی حقیقت موجب آپ اہیسی سلسلہ کے تھے جیسا کہ اُن کے ابا و اجداد کے نقل منقول ہے آپ جوانی کے زمانی مین سماع کے طرف زیادہ مائل تھے اور ایک دن جب آپ سماع میں مشغول تحے تو اُن کے بڑے بھائی میان سید جلال جو خود وقت کے بڑے عارف تھے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے گال پر تھپڑ ماردی اور وہاں سے جبرن لیکر چلے آئے آور اپنے نیک سیر والدہ ماجدہ کے پاس پیش کیا، اور کہا کہ میں تو کوئی علم حاصل نہ کرسکا اور اپنے آپ کو ضایع کردیا اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ پڑحے فقط سماع میں وقت ضایع کرے جو بلکل نہ مناسب ہے کہتے ہیں کہ اُس وقت حضرت جی نے یہ بیت پڑھا۔
ان در سندي مڱڻڳ، اڳي ايئن نه هير
جيئن ڊگها ڪري پير، سڄيون راتيون سمهي
ترجمہ: اُس درگاھ کے مانگنے والے کی عادت نہ تھی کہ ساری رات اپنی پاؤں کو دراز کر کے سوتا رہئے مزید روایت کرتے ہے کہ حضرت میاں جلال نے جب حضرت جی کو اسی طرح تھپڑ ماری تو والدہ نے اُن پر ناراض ہوگئی اور کہا کہ آئندہ شاہ کریم کو دوبارہ کھ نہ کہنا کیونکہ تمہیں اس کے مرتبہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے یہ کہ کر والدہ نے یہ قصہ سنا: ایک دفعہ عارف بااللہ سید حیر مثالوی کی بہینسیں گم ہوگئیں تھین اُن کے بیٹوں نے بہت تلاش کیا لیکن مایوس اور دلگیر ہو کر بیٹھ گئے اخر میں حضرت رسالت مابﷺ غیب کے پڑدے سے اُن کی خبر گیری کی خاطر اُن کے گھر تشریف فرما ہوئے میں اُس وقت شاہ کریم کو لیکر اپنے آپ حضور کریم ﷺ اُسی گھر سے باھر نکل تمہیں بھی گھر کی ڈیوڑی میں ایک طرف ہونے کی کوشش کی تو آپ ﷺ نے فرمای کہ دور مت جائے تو اُس وقت میں نے شاھ کرعم کو اٹھاکر میں نے اُن کے سامنے کیا تو آپ ﷺ نے لواعب مارک اُن کے منوں میں ڈالا اور اُس کے بعد چلے گئے مطلب کے یہ بزرگی و بھلائی سب اُس بات کا نتیجہ ہے
حضرت جی کے مرتبہ کا دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے جو اِس طرح ہے کہ والدہ فرمایا کہ شاہ کریم ابھی میرے پیٹ میں تھے کہ ایک دن حضرت رسالت ماب ﷺ نے غیب کے پڑدے مین سے اپنا چہرہ مبارک دکھایاجس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر روشن اور پُر ہوگیا ۔ میں نے دیکھا کہ شاہ کرم کو اُٹھاکرمیرے ہاتھوں میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ ہماری امانت اِس کا خیال کرنا، اور اِن کا نام عبدالکریم رکھنا، میان سید جلالا نے کہا کہ میں نے والدہ کی یہ بات سننے کے بعد میں شاہ کریم کو پھر کبھی کچھ نہ کہا بلکے وہ جو چاہتا تھا، وہ کرتے رہتے تھے، اور میں اُن کے اِس رویہ کو قبول کرتا رہا، آخر کار میں نے اُن کو کہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اُس وقت تک تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اُسی طرح تمہارے بالبچوں کی ذمیواری بھی مجھ پر ہے مطلب کہ حضرت جی کی خدمت کرتے رہتے تھے اور یہاں تک کہ اُن کے لیئے پانی کے لوٹے بھی بھر کے رکھتے تھے کہتے ہیں کہ جب تک میاں سید جلال زندہ تھے تو شاہ کریم فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں رہتے، اور اُن کی خدمت کرتے رہئے جب میاں جلال اِس فانی دنیا سے دارلمقا کی طرف متقل ہوگئے اس کے بعد حضرت حضور فرمودہ کے مطابق اپنے اہل و عیال کی خدمت میں مشغول ہوئے ورنہ شاید بھی ھر گز نہ کرتے ، ہدایت موجب روحانی تربیت بیھار کے علائقے کے ایک ایسے فقیر سے حاصل کی جو اُس وقت سندھ میں تشریف فرما ہوئے تھے جو اِس سلسلے میں روایت ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک دن اُن کے جوانی کہ زمانہ میں اُن کے گاؤں کی مسجد میں آکر ٹھرے انہوں نے بتایا کہ اُن کا تعلقہ بیھار کے علائقے سے ہے جو ھندستان کا ایک صوبہ ہے
در اصل وہ شخص عارف یکتا مرشد زمانہ کتب وقت پیرے بینظیر صاحبت تجرید و نفرید اور اظھائے الاھی کے امین اور خدا کی نعمتوں سے برزید شخس تھے میں اُن کی خدمت میں دن رات مشغول ہوگیا اور جب مجھے معلوم ہو کہ وہ مرغہ کہانے کا شوقین ہے تو میں نے مرغوں کا ایک لشکر پالا اور پھر ھر روز ایک مرغہ زبح کرکے بنھون کر کے اُن کی خدمت میں پیش کرتا تھا مطلب یہ کہ ان کی خدمت میں کوئی کثر نہیں چھوڑی، تقریبا چھ ماہ وہ اُسی مسجد میں رھئے ایک دن انہوں نے اپنا اقوال اس طرح بتایا کہ:
میں اصل میں ایک سپاھی تھا میرے عزیز رشتہ دار بڑے خشحال اور بڑے مالدار تھے، ایک دن اپنے بھائیوں کے ساتھ ملک کر جنگ کے لیئے نکلا اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جب دونوں طرف سے جوان گرنے لگے تب میرے ہاتھوں اتنے لوگ مارے گئے جو اُن کے خون سے میرے تلوار کا ھتھیابرف کی طرح ہاتھ میں جم گیا اور اس وقت خدا کے خوف نے ایسا گھیرائو کیا کہ میں اُن کی محبت کے غلبے میں آکر اپنے آپ کو کہنے لگا کہ خدا نے تمہیں مخلوق کے قتل کے لیئے تو پیدا نہیں کیاہے ، اُس وقت ہی گھوڑے سے اُترا اور لغام بھائیوں کے حولاے کر کے اپن کو کہا کہ میں آرہا ہون ، یہ بہانا کر کے بھائیوں سے بھاگ نکلا اور جھنگلات اور ریگستانوں سے گذرتے ہوئے کسی جھنگل میں پھس گیا جہاں فقط ہاتھی ھی ہاتھی تھے، اِسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں دن کو درختوں کے پتوں میں چھپ کرکے گذارتا تھا رات کو پیادل چلتا رہتا تھا آخر دن رات ایک کر کے اُس خوفناک جنگل سے باھر نکلنے مین کامیات ہوگیا اور ایک نے صھر "آبی" اکر پہنچا اِسی طرح کئی شھر اور علائقے دیکھتے اور قدر کے عجیب مناظر کا مشاھدہ کرتے کرتے شھر شھر گھومتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور وہاں سے جیسے ہی گھوڑے سے اتر کرباہر نکلا ہوں تو ایک گھڑی بھی واپس جانے کا خیال نہیں کیا ۔
اپنے احوال دینے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہاں آپ کے ملک میں کون سے بزرگ اور درویش ہیں اور وہ کس طرح خد کو یاد کرتے ہیں میں نے اُن کو بتایا کہ ایک مخدم نوح ہے دوسرے سید نیراں یوسف بکھر جو ٹھٹہ شھر کے یا تقر ایک پھاری پر رہتے ہیں اُس کے علاوہ اُس وقت کے دوسرے کئی مشھور اور معدوفون درویشوں کے نام لیئے اور ان کے ذکر و فکر کا طریقہ انہیں بتا اُن سب میں سے سید نیراں یوسف بکھری کے ذکر کا طریقہ انہیں بہت پسند آیا اور بعد میں اکےر ان کے طریقے ذکر کی تعریف کرتے تھے آخر ایک دن اُس شخص نے مجھے ذکر کی تلقید کی اور جواب یہ فرمایا کہ یہ راض کسی کو مت بتانا میں نے یہ بات قبول کی لیکن ایک دن اچانکہ زبان سے وہ بات نکل ھی گئی اُس کے بعد جب مسجد میں، میں اُن سے ملنے گیا تو وہ وہاں سے جاچکے تھے اُس واقعے نے مجھے بہت ملول اور دلگیر کردیا۔ میرے لیئے پوری دنیا اندھیرا بن چکی تھیں، اور تمام عیش و عشرت زحر کی طرح محسوس ہونے لگے اُسی فکر میں حیران ور سرگردان رہا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ وہ سید میراج یوسف کے پاس گئے ہوں یہ سوچ کر مسجد سے بار نکلا اور گھر کی طرف اور گھر کی طرف بھی نہیں گیا سیدھا ٹھٹہ کی طرف رخ کیا کے کئ گاؤں اور "گوٹھوں" سے گزرتے ہوئے تکلیف اور مشکلات برداشت کرتے کرتے بل آخر سید یوسف کے دائرے میں پہنچ ہی گیا تھا کے بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اگلی پچھلی تمام تکالیف بھول گیا، قریب جاکر اُن کے چہرے مبارک اچھی طرح سے دیکھنے کی کوشش کی تو اُن کے بلند درجات اور شرح سدر کا احساس ہونےلگا، میں ابھی سوال کرنے والا ہی تھاکہ آپ فرمانے لگے کہ سید میراں یوسف کی جو تعریف سنی تھیں وہ سب شچی تھیں، بلکہ انہیں اُس سے بھی زیادہ بھایا، تنھائی میں ملاقات ہوئی تو وہ سب کچھ میں نے سنایا جو شروع سے آخر تک میرے ساتھ گذری اچانک جب اُن کی نظر میرے ننگے پاؤں پر پڑی تو اپنے جوتے اُتار کر مجھے پہننے کے لیئے دیئے اور کہا کہ حج پر جا رہئے ہیں اُس لیئے تکلیف کے باعث میں نے وہ لیکر اپنے پاس رکھے، لیکن پہننے کی ہمت نہ ہوتی بلکے سوغات سمجھ کر سینے کے ساتھ لگا کر رکھا خیال کیا کہ انہیں اپنے سر پر تاج سمجھ کر رکھونگا ہرچند کے سید میراں نیو سنو نے مشورہ دیا کے پاؤں میں پہن لو میں نے یہ بات قبول نہیں کی پھر بعد میں فرمای کہ اچھا تو اُس سے ٹوپی بنوا کر سر پر رکھو۔ میں ٹوپی ساز کے پاس جاکر اُس ٹوپی اور سرپے پہن کر ُن کے حضور میں حاضر ہوا یہ دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئے اور مسئلے کے نیچچے پڑے ہوئے پیے نکال کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا کہ اس رقم سے ٹھٹہ شھر سے روٹیاں لیکر آئوں میں نے وہ پیسے تبرق سمجھ کر اپنے پاس رکھے اور اپنے پیسوں سے روٹیان لیکر آیا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، یقین ہوا کہ آپ وہاں سے چلے گئے ہیں مجے اُ سے بڑا جھٹکہ لگا جیسے زمین پاؤں سے نیچے نکل گئی ہو اور پہلے کی خوشی غم میں تبدیل ہوئ روٹی سر پر رکھ کر انہیں ھر گاؤں اور بستی تلاش کیا آکرکار بڑی ور بدری کے بعد بندر کے شھر جو سندھ کا ھی شھر ہے وہاں پر انہیں تلاش کرلیا اُس وقت کشت پر چڑھ کر روانہ ہونے والے تھے میں نے بھی وہ تمام روٹیاں اور کھانے کا سامان لھول کر اُن کے آگے رکھا اور خود ادب کے ساتھ کھڑا ہوگیا، مجھ دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراھٹ آگئی اور تکالیف کی حالت میں دیکھ کر ھمدردی کرنے لگےاور مجھے ایک کھڑا ہاتھ میں دے کر کہنے لگے کہ جاؤ جاکر اپنے اھل و عیال کے لیئے خوراک خرید کرو جب میں نے وہ کھڑا اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ سونے کا بن کگیا میں نے عرض کیا کہ میں سونے کے واسطے آپ کے پیچچھے نہیں لگا ہوں، اُس پر آپ مزید مھربان ہوئے اور فرمایا کہ واپس چلے جاؤ میں نے کہا آپ کے خدمت کیئے بغیر مجھے کوئی قرار اور آرام نہیں ملے گا بلکہ پریشان گذاروں گا لحاظ میے حق میں دعا فرمائیے اُس پر فرمایا کہ جاؤ دو تین میلوں کے بعد تمہارے دل میں عشق خداوندی کی وہ شمع جلے گی جسے توں خوش گذارے گا البتہ ابھی تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اور میرے بدلے اپنے اہل و عیال کے خدمت میں مشغول ہوجاؤ اپنے زبان مبارک سے یہ الفاط کہے کہ الوداع کر کے روانہ ہو گءے اور میں اپنے آپ کو انتھائی بے یارو مددگار محسوس کرنے لگا اُس دوران میں اُن کی تلاش میں کئی مرتبہ پیر آروٹ کے پاس شیخ پٹھوی کے مقبرے میں گیا وہاں میں نے ایک کونے میں چار فقیروں کو دیکھا اُن میں سے ایک اٹھا اور کشتا ہاتھ میں اُٹھا کر گدا کے لیئے پیرآر شھر کی طرف گئے اور جلد ہی اُس کو کھان کی چیزوں سے بھر کر واپس آئے پھر وہ کھانے ان میں سے ایک فقیر کے آگے رکھا گیا جس نے اُس کھانے کے 5 حصے کیئے 4 آپس میں تقسیم کر کے حاصل کیئے اور ایک حصہ میرے لیئے رکھا جب سے وہ لقما کھایا ہے اُس کے بعد کہانا کہانا یا نہ کھانا میرے لیئے برابر تھا، یعنی وجود میں سے بشرطیہ کی صفت ختم ہوگئی ہے
دوسری روایت ہے کہ اُن فقرا میں سے ایک نے زمین سے ایک لکڑی اٹھا کر مجھے دی جس کے چوسنے کے بعد میرے اندر سے کھانے کی اشتہا ختم ہوگئی شاہ کریم کے اُن بزرگوں کے علاوہ اُس زمانے کے بڑے عارف اور کتب مکدوم نوح رحمتہ اللہ علیہ اور ولی الثر سید میران یوسف بکھر جو ٹھٹہ کی رہنے ولاے تھے اور مخدو آدم سمیجو جو فلا گوٹھ میں رہائش پزیر تھے جو اپنے وقت کے ولی تھے ان سے خاص صحبت رہئی۔
فصل دوم:
شاہ کریم کا مرتبہ اور مقام معلوم ہونا چہایئے کہ حضرت جی کے اتنے درجات ہیں جو کہ تحریر کع گرفت سے باھر ہیں البتہ جو کچھ سندھ کے بزرگوں نے بیان کیا ہے اُس کا یہاں ذکر کرتے ہیں مشھور بزرگ اور عارف حاجی شورو جو "جونا" کے علائقے ورھ نامی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کا کہنا ہے کہ تمام بزرگان اور اولیا کرام خدا تعالیٰ کے تعلقی کچھ ساعتین نصیب ہوتی ہیں، لیکن حضرت جی کو اِس کے لیئے دائمی وقت ملا ہوا تھا، اور جس کی اسی کو خبر نہ تھی ، دوسری مرتبہ حاجی صورو کے پاس ایک قفیر نے آکر بتا کہ حضرت جی کے مرید کہتے ہیں کہ ہم خد اتعالیٰ کا مشاھدہ کرتے ہیں آپ بتائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا اپنی دعوٰ میں تھوڑے بہت سچے ہیں کہا کہ بلکل سچ ہے، ہم نے بھی اے بزرگوں کی خدمت کی ہے مثلا مخدوم اسماعیل جاگو اور سید دکن الدین رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ لیکن کہیں سے بھی گوھر مقصود حاصل نہیں ہوا، جب حضرت جی کی کدمت میں آکر ھاہوا اور عرض کیا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ سے کہا کہ "وہ" ہے یا نہیں 1 بس لفظ " این" یعنی "وہ" کہنے سے مجھے اصل متوجہ حاصل ہوگیا اس لیئے ہر وقت جو معتدقدین حضر جی کی خدمت میں رہتے تھے ان کو وہ مرتبہ اور مقام کیوں نہیں ملے گاکہتے ہیں کہ حاجی صورو کے کئی مرید تھے لیکن جب حضرت جی کی خدمت میں آئے تو ان پر حضرت جی کی نگاہ کا تنا اثر ہو اجو کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کو مرید بنانا مناسب نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ آج سے ہم خود حضرت جی کے مرید ہیں اور آپ لوگ بھی مرید ہیں، اُس کے بعد مریدوں کو نصیحت فرمائی خبردار ایس کے بد دوسرا خیال دل میں مت لانا صابو سومرو جو کتب زمانہ مخدوم نوح رح کے خاص مریدوں میں سے تھے اُن کا کہنہ تھا کہ ھر ولی کا ایسا وقت مثیر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے مشاھدے سے اُن کا وصال ہوتا ہے لیکن حضرت جی اگر کبھی زمین پر تھی درا ہوتے تھے تب حق کے متن حدے میں محو ہوتے تھے، ایک دوسری روایت ہے کہ دورو بیت بھاو لادین کو دڑ بوجو بھی مخدوم نوح رحمتہ اللہ علیہ کےخا شلفا میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک میں حضرت جی کے اِس آیا اور عرض کیا کہ سائین جس نظر سے آپ خدا کا درشن کرتے ہو میرے اوپر بھی وہ نظرِشفقت فرمایو، یہ بھی کہتے تھے کے میری ہمیشہ سے تمنا رہی ہے کے حضرت جی نے صحبت کا ایسا موقعہ مل جائے جب کو ئی اور موجود نہ حہ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت جی کہ ایک طرف ہوکر سونا ہمارے لیئے کئی عبادتوں سے بھتر ہے حضرت جی خدا کی راہ کو اتنی طئہ کرتے ہیں کہ اس کا زندان انہی کو ھی ہے جس کا ہمیں کوئی انداز نہیں بھاؤ الدین گودڑیو نے کہا کہ میں نے جو اولیائے کرام کے بارے میں رسالے مرتب کیے وہ حضرت جی ھی سمجھتے تھے۔اِس لیئے اُن کی وفات کے بعد بھی میں نے انہیں کبھی کھول بھی نہیں دیکھا ، روایت ہے کہ اپنے زمانہ کے عارف اور شیخ حضرت میان سید ابراھیم ولد پیر طریقت حضرت سید یوسف جو میان سید جعفر کے دادا تھے اور انہیں حضرت جی کے پاس بڑی پذیرائی تھی، ان کا کہنہ ہے کہ جس دن سے حضرت جی محبت اور شوق کے گھوڑے کو قصویا کے ۔۔ سے دوڑایا ہے اس وقت سے ان کے لغام میں کبھی ڈمیل نہیں آئی، میان ابراھیم واحد مخدوم نوح کا قول ہے کہ ھمیں فن و حکمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے لیکن حضرت جی کے زمانے کے لقمان حکیم ہیں۔ اور انہیں تمام فنون اور ھنر میں مھارت حاصل ہے روایت ہے کہ ایک دن عارف زمانے اور دانشمند مخدوم ضیاالدین وعض فرما رہئے تھے اور حضرت جی اُس وقت اب صغیر پن میں تھے، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر وہ وعض سن رھئے وعض ختم ہونے کے بعد جیسے ھی شاہ کریم اٹھ کر چلنے لگے تو مخدوم صاحب کی نظر اُن پر پڑی تو دیکھتے ہی فرمانے لگے سبحان اللہ یہ لڑکا اِس عمر میں ھی حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں ہے اگر میں جوان میںدیکھان تو کتنا اچھا ہوتا روایت ہے کہ ایک درویش مھران نھرعہ جو خود بھی زبرگی اور درویشی میں بڑے نامور تھے اپن کے مرشد فوت ہوگئے کچھ عرصے کے بعد انہیں حضرت جی قدم بومی کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت جی سے اتنے متاثر ہوئے کہ حاضرین کو مخاطب ہوتے کہا کہ مدت ہوئی ہے کہ میرے شوھر فوت ہوگئے اور میں بغیر شوھر کے تھا لیکن اب میں آپ سب گواھ بنا کر حضرت جی کو اپنا شوھر قرار دیتا ہوں یعنیٰ انہیں اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں اور اپنی گردن اُن کی غلامی میں دیتا ہوں درویش صالح سومرو سے روایت ہے کہ حضرت جی کے لیئے لذیذ طعام اور قیمتی لبا اُن کی فقیر والی طبع کے لحاظ سے برابر تھے یعنیٰ ان کی طیعت پر ان کا کوئی اثر ہوتا تھا لیکن دوسروں کی وجھ سے نہ کبھی ایسا کہانا کہاتے تھے نہ ہی ایسا لبا پہنتے تھے بلکے پیوند لگے ہوئے کیا سب یہ قناعت کرے تاکے مریدوں کے قیمتی لباس اور اچھا کہانا ضروری نہ ہوجائے روایت ہے کہ درویشی رنگ میں رنگےہوئے پیرے طریقت میان عبدالعزیز جو ڈاڈون کے رہنے والے تھے ایک دن حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر با ادب کھڑے رھئے حضرت جی نے فرمایا کون کھڑے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ عبدالعزیز ۔۔ اس پر فرمایا خوش آمدید اُس کے بعد ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ، عبدالعزیز کہنے لگے کہ جب سے آپ کا یہ قول سنا ہے کہ زخمی کو مزید زخم نہ دینے چاہیئے تب سے سچی دل سے آپ کے پیچھے آپ کا مرید بن گیا ہوں، ایک دن اُسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت جی اور بھاؤالدین گودوڑ کے بارے میں تمہاری کیا رئے ہے تو کہنے لگے کہ بھاالدین کسی زندہ کو تہ مار سکتے یں لیکن مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے لیکن حضرت جی ولایت اس منزل پر ہے کہ فانی فلا اور عارف بالا میاں عیسیٰ رح جو حضر جی کے تمام پیارے مریدوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کئی ملک دیکھے بڑی محنت اور مشقت سے گذارے اور کئی بزرگوں کی خدمت کی پہیاں ۔۔۔ آخر بیزار ہوگیا کہیں سے بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا آکر کار جب حضرت جس کے حاضر ہوا تو وہاں تمام مشکالت اور دربدری سے جان کلاصی ہوئی اور مجھے اپنی مل گئی روایت ہے کہ شروع والے دنوں میں حضرت جی خدا کی تلاش اور طلب میں کسی عرف میں جاتے تھے ایک دن دریا کے کنارے پر پہنچے وضو کرکے نفل نماز میں مشغول ہگئے جب نماز پوری کر کے دائیں طرف سلام پھیرا تب اُن کو اُس طرف کی دنیا اور اس کے حقائق کا کشف حاصل ہوا اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرا اس طرف جو کچھ تھا اُ سے باخبر ہوگئے ۔
درویش صابو سومرو کہتے تھے کہ حالا کنڈی جو مخدوم نوح رح کی رہائش ہے وہ بھشتے اور لے اور حضرت جی کی رہائش "بہشتے ثانی" ہے درویش احمد سے روایت ہے کہ جو فرد حضرت جی کے صحبت میں آئے تھے چاھے ایک مھینہ رہئے یا ایک ھڑی جاتے وقت وہ رہتے جاتے تھے اور حضرت ج کی صحبت وہ چھوڑنا ان پر ناگوارا گذرتا تھا۔
اُس وقت کے نامور عالم یان عبدالرشید بصید سے روایت ہے کہ ہم جب حضرت جی سے کوئی نقطہ سنتے تھے ایسا محسوس ہوتا تحا کہ معلوم نہیں معنیٰ اور فھم کے کئی دفتر کھل جاتے تھے، روایت ہے کہ ایک دن راتے میں چلنے ہوتے فقیر بھا الدین گودڑ پر نے زمین سے کھجور کا آدھا ۔۔ دیکھا جسے اُس نے ہاتح سے اُٹحالیا اُن سے پوھا کہ یہ آپ نے کوں آٹھایا تو جواب دیا کہ اِس پر الف لکھا ہوا ہے یہ بات جب حضرت جی نے سنی تو فرمائی کہ کون کون سی چیز میں ہے اٹحا/یں کیونکہ ہر چیز پر خدا کانام لکھا ہوا ہے بیچارے بھاؤ الدین نے تو فقط کھجور کی کٹلی پر اُسے دیکھاروات ہے کہ ابو بکر ولد با یزدی ایک بزرگ اور پہنچے ہوئے شخس تھے اور وہ سونڈا کے رہنے والے تھے ان بیٹےسے روایت ہے کہ وہ ہر وقت وجد اور حال کے غلبے کے تحت رھئے تھے اور جب بھی یہ فیفیت ان پر طاری ہتی تھی تو ھمیں بلا کر کہتے تھے کر جاو حضرت جی کی خدمت میں پہنچو ایک دن ایکد ن اُن ویسی کیفی طاری ہوئی اور ھمیں نہایت تاقید سے کیا جا حضرت جی کی خدمت میں اُس کیے بعد یہ واقعہ اُن کے زبان پر آیا کہ ایک دن میں اپنی کھیتی میں بیٹحہ ہوا تھا کہ اچانک دیکحا کہ آسمان پر بادل آگئے ہیں اور ان بادلوں میں سے ایک صخص نظر آئے جس کی نوری نظر سے مجھے نجلی الاھی حاصل ہوئی اور وصالی خدا میسر ہو۔ اُسی کیفیت کے سبب میں ۔۔۔۔ دیوان ہونے والا لیکن موال کی مھدیا ۔ ہوتی اُس شخص نے مجھے ھدایت کرتے ہوئے کہا اے میرے وسال کے بار میں کوئی بان کرے موصال کس طرح ہے ہر لفط سن کر میرے ہوش ٹھکانے آگئے اور میں کچھ نہ کہا اُس پر فرماتے ہیں کبھی کبھی وصال ہوتا ہے لیکن حضرت جی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اُن کی آنکہین دائمی طور پر خدا کے وصال میں محو رھتی تھیں فرمای کہ جی ، یہ بات صحیح اور اِس میں کوئی شک نہیں اُس کی ماں اسی طرح جیسے مگرمچھ ھمیشہ پانی میں رہتا ہے اور کبھی کبھی باھر نکل کہ آنکھین لھلتا ہے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے مقصد کے خاطر پیر پٹھو رح کے مقبر میں آکر بیٹھ اور عبادت کرنے لگا اور رات کو خواب میں انہیں ایک بزرگ نے کہا کے خلق خدا کے لیئے اپنے مفاصد حاصل کرنے کی خاطر حضرت جی کو طرف رجوع کر رہی ہے تم یہاں بیٹھ کر کای کر رہئے ہو جیسے ھی خواب سے بیدار ہوا تو سیدھا آکر حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوا اور جلد ھی ان کے خاص مریدوں میں شمار ہونے لگا۔